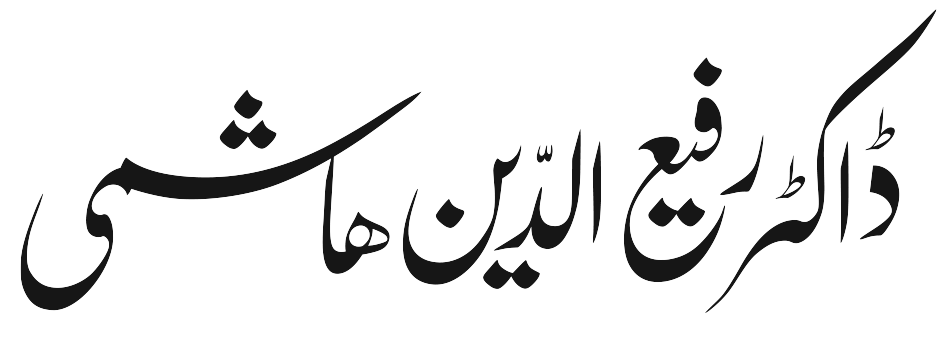شمس الرحمن فاروقی :باتیں اور یادیں
(تحریر: ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ) فاروقی صاحب سے پہلی ملاقات حیدر آباد دکن کے اقبال سیمی نار(19۔20،اپریل 1986ء) میں ہوئی ۔ سیمی نار میں ان سے گفتگو کرنے اور ان کی باتیں اور تقریریں سننے کا موقع ملا۔ دوسرے روز وہ حیدر آباد سے واپس جانا چاہتے تھے لیکن راقم کا مضمون سننے کے لیے کچھ دیر رکے رہے ۔جونہی مضمون ختم ہوا، وہ اٹھ کر چل دیے۔آئندہ برسوں میں فاروقی صاحب سے دو تین خطوں کا تبادلہ ہوا۔ 2004ء میں وہ اقبال اکادمی پاکستان کی دعوت پر پاکستان آئے۔ اس دورے میں انھوں نے How to read Iqbal کے موضوع پر اکادمی میں ایک مفصّل لیکچردیا ۔ لاہور میں ان کے اعزاز میں متعددّ تقریبات منعقد ہوئیں۔ایک تقریب کا اہتمام ڈاکٹر تحسین فراقی صدر شعبۂ اردو نے سینٹ ہال پنجاب یونی ورسٹی میں کیا ۔ایک اور تقریب گورنمٹ کالج یونی ورسٹی میں منعقد ہوئی۔ فاروقی صاحب اردو اور انگریزی کے بہترین مقرر تھے۔راقم کو متعدد بار ان کی اردو اور انگریزی تقریریں سننے کا موقع ملا۔ اردو تو ان کی مادری زبان تھی۔اوائل عمر ہی سے انھیں انگریزی پر بھی دسترس حاصل تھی۔کراچی کے ظہیر خان جمنا کرسچین کالج الٰہ آباد میں فاروقی صاحب کے کالج فیلو تھے ۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1965ء میں فاروقی صاحب کو اپنے مادرِ علمی میں کسی جلسے میں بطورِ مہمان خصوصی بلایا گیا۔سفید شیر وانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھے۔ لگ رہاتھا کوئی شاعر ہیں مگر انھوں نے انگریزی میں ایک دھواں دھار تقریر کی تو سارے طالب علم ششدررہ گئے کہ شیروانی پہن کر بھی اتنی اچھی انگریزی بولی جا سکتی ہے ۔ ذکر تھا ان کے 2004 ء کے دورۂ پاکستان کا ۔ نوائے وقت نے ان سے ایک خصوصی مکالمے کا اہتمام کیا۔ عمران نقوی میزبان تھے اور پینل میں عزیز ابن الحسن ،ضیاء الحسن اور جعفر بلوچ کے ساتھ راقم بھی شامل تھا۔بھارت میں اُن کے مصاحبوں پر مشتمل کتاب فاروقی محوِ گفتگو شائع ہوئی تھی ،معلوم نہیں اس میں یہ انٹرویو شامل ہے یا نہیں؟ 2007ء یا 2008ء میں وہ فیض سیمی نار میں شرکت کے لیے لاہور آئے۔ لمز میں قیام پذیر ہوئے۔ انھوں نے سیمی نار میں کلام فیض کی ہمہ نوع خامیوں اور کمزوریوں کی نشان دہی کی۔ ترقی پسندوں کو صدمہ ہوا۔ زاہدہ حنا کو زیادہ ہی رنج ہوا۔فراقی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ رونے لگیں ۔فاروقی صاحب نے کہا: میں تو عرصے سے اس طرح کی باتیں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ علمی معاملہ ہے۔ اس میں ذاتیات کا دخل نہیں۔ 2010ء میں وہ لاہور آئے۔ قیام لمز ہی میں تھا۔نوائے وقت میگزین کے انچارج صاحب(نام بھول گیا) اُن سے انٹرویو لینا چاہتے تھے۔فاروقی صاحب اُن سے واقف نہ تھے۔انچارج صاحب نے مجھے ذریعہ بنایا۔ میں نے فاروقی صاحب سے وقت لیااور اُنھیں لے کر پمز پہنچا۔کہنے لگے: صرف15، 25 منٹ۔۔۔ خیر ، سوال جواب ہونے لگے۔ تقریباً پون گھنٹا انٹرویو ہوتا رہا۔ نوائے وقت میگزین میں چھپا۔ افسوس ہے اس کی نقل محفوظ نہ رہ سکی۔ 2010ء میں راقم نے اُنھیں حسبِ ذیل کتابیں بھیجیں: ۱۔ مکاتیب مشفق خواجہ بنام رفیع الدین ہاشمی ۲۔ مکاتیب رشید حسن خاں بنام رفیع الدین ہاشمی(مرتب :ڈاکٹر ارشد محمودناشاد) ۳۔ سیّد ابوالاعلیٰ مودودی بحیثیت نثر نگار (محمد اصغر جاوید) جواباً انھوں نے 7 جون کے خط میں حسبِ ذیل تبصرہ کیا: ’’مشفق خواجہ اور رشید حسن خاں کے خطوط میں نے سب پڑھ ڈالے۔ آپ کے حاشیے نہایت عمدہ ہیں۔ ارشد محمود صاحب نے اتنے اچھے حاشیے نہیں لکھے۔ خیر۔ مولانا مودودی پر کتاب اِدھر اُدھر سے دیکھی۔ سوانحی حصّہ زیادہ توجّہ سے پڑھا۔ کام بہت بڑا اور قابلِ قدر ہےلیکن اب مجھے مولانا کے افکار سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔ کبھی دلچسپی تھی اس وقت یہ کتاب ملتی تو حرزِ جاں بنا لیتا۔ مجھے ان کی کتابوں میں خلافت و ملوکیت سب سے زیادہ قابلِ قدر اور اہم معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میں مولانا کے میدان یعنی اسلامیات اور اسلام بطور تحریکِ حیات ، میں دخل در معقولات دینے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ مشفق خواجہ کے خطوط دلچسپ ہیں اور آپ کے حواشی نے انھیں یادگار بنا دیا ہے۔ مشفق خواجہ اور آپ دونوں کے علم کی وُسعت اور تجربے سے واقف تھا، لیکن ان مکتوبات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت میں علم اور ذوقِ علم کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ رشید حسن خاں کے مکاتیب زیادہ تیکھے اور زیادہ ذاتی ہیں۔ ان کی شخصیت اور علمیت دونوں ہر جگہ عیاں ہیں۔ مشفق خواجہ کے خطوط پر آپ کے حاشیے میرے لیےیوں بھی بہت کارآمد نکلے کہ آپ نے ان لوگوں کی تاریخِ ولادت اور وفات درج کرنے کا اہتمام کیا جن کے نام ان خطوط میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ کام اردو والے تو تقریباً بالکل نہیں کرتے۔ غیر زبانوں میں بھی اتنا اہتمام کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں ایک تاریخ نامہ Date List مرتب کرتا رہتا ہوں ، نہایت سادہ، صرف تاریخِ ولادت اور موت، اور تعارف میں صرف ایک لفظ ۔ کئی نام میں نے اپنی فہرست میں آپ کے حواشی سے لے کر اضافہ کیے۔ لیکن بعض ناموں کے سلسلے میں الجھن بھی ہوئی کیونکہ آپ کی درج کردہ تاریخوں اور میری درج کردہ تاریخوں میں تفاوت نظر آیا۔‘‘ فاروقی صاحب نے جو گوشوارہ بھیجا تھا ۔راقم نے، اس کی روشنی میں تاریخیں درست کر لیں۔ ڈاکٹر کبیر احمد جائسی (16 نومبر 1934ء- 7جنوری 2013ء)اردو اور فارسی کے عالم اور سکالر تھے۔ جناب شمس الرحمن فاروقی کو جائسی سے خصوصی تعلق ِخاطر تھا۔ اس کا اندازہ جائسی کے نام ان کے خطوں کے مجموعے (شمس کبیر۔القرطاس کراچی، 2004ء) سے ہوتا ہے ۔مجھے ان کی وفات کی خبر ڈاکٹر نگارسجاد ظہیر صاحبہ نے دی۔ جائسی مرحوم ،نگار صاحبہ کے ماموں تھے۔ میں نے فون پر نگار صاحبہ سے تعزیت کی اور دوسرے دن فاروقی صاحب کو بھی برقی ڈاک سے تعزیتی خط روانہ کیا۔ اسی روز ان کا حسب ذیل جواب موصول ہوا: Dear Brother Rafiuddin Hashmi, Yes, It was a great shock. The New Year has not begun well for us who lost numerous major writers in 2012. Yes,
نصیر احمد بٹ صاحب
تاریخ پیدائش: 15دسمبر1941 مولد:تیجہ کلاں گورداسپور ۔ والد: عبد الغنی چھ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ہجرت:1947میں اپنے والدین، چھوٹی بہن اور پانچ بڑے بھائیوں کیساتھ خاک و خون کا دریا عبور کرتے ہوئے نارووال کے قصبہ بدوملہی میں آباد ہوئے۔ تعلیم: بچپن میں ہی اپنے چچا حکیم عبدالرحمٰن خلیق مرحوم سے ترجمہ قرآن پڑھا۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول بدوملہی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ۔ بدو ملہی کو قادیانیوں کے غلبے کیوجہ سے ربوہٰ ثانی بھی کہا جاتا ہے 1952 میں گیارہ سال کی عمر میں قادیانیوں کی عبات گاہ کے تھڑے پر کھڑے ہو کر ختم نبوت پر تقریر کر کے اپنے قصبہ میں قادیانیوں کیخلاف تحریک کا آغاز کیا اور اپنے بزرگوں اور بھائیوں کیساتھ مل کر قصبہ میں موجود واحد سکول جو کہ قادیانیوں کے زیر انتظام تھا کے مقابلے میں مسلمانوں کے اسلامیہ اسکول کے قیام کی تحریک چلائی تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفےٰؐ اور مارشل لاء کیخلاف تحریک میں سرگرم حصہ لیا٠ دورانِ تعلیم علامہ اقبال اور سید مودودی کے مرید بنے۔ اقبال کےاردو کلام کے علاوہ فارسی کلام کا مطالعہ کیا برسوں مولانا مودودی کے مبارک مسجد کے درس اور ذیلدار پارک اچھرہ کی عصری محافل سے علم وعمل کے موتی سمیٹتے رہے۔ مولانا مودودی کے سارے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور مرتے دم تک تفہیم القرآن کے روزانہ مطالعہ کا معمول جاری رہا، DYF کے سرگرم کارکن رہے روزگار: میٹرک کے بعد 1958 سے سرکاری ملازمت کے سلسلہ میں لاہور میں رہے۔ رزقِ حلال کیلئے ملازمت کیساتھ ساتھ زرعی اجناس کی تجارت کرتے رہے۔ اچھے تیراک تھے سیلاب میں کئی افراد کی جانیں بچائیں اور جماعت اسلامی کے رفاعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا 1973 میں فیملی کیساتھ وحدت کالونی لاہور میں شفٹ ہو گئے سرکاری کوارٹر پر بھی جماعت اسلامی کا جھنڈا لگا کر رکھا توحید باری تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین تھا لین دین کے بہت کھرے تھے یہاں تک اکبری منڈی کے تاجروں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر میں آپ کو مقررہ دن پر ادائیگی کیلئے نہ پہنچ سکوں تو مجھے فون کرنے کی بجائے منصورہ آ کرمیرا نمازِ جنازہ پڑھ لینا اور میرے بیٹے سے اپنی رقم وصول کر لینا۔ اللہ کری نے انکے لین دین کے کھرے پن کی اسطرح لاج رکھی کہ وفات سے چند دن پہلے منصورہ مسجد کے ایک نمازی کیلئے اپنے ایک دوست سے پچاس ہزار کی رقم ادھار لی، وفات سے چند دن پہلے بیماری کیوجہ سے یاد داشت کھو بیٹھے تھے اس دوران جیسے ہی طبعیت بہتر ہونے سے یادداشت بحال ہوئی تو فوراً اپنے دوست کو واپس بلایا اور اسے رقم واپس لوٹائی۔ مستحق عزیز و اقارب کا خیال رکھتے اور بیوہ خواتین کی مدد کرتے تھے۔ اولاد: تین بیٹے۔ علامہ محمد اقبال رح اور مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ سے عشق تھا سید منور حسن رحمہ اللہ اور ابوالشہداء ملک نواز صاحب سے بوجہ للہ عقیدت رکھتے تھے تاریخ وفات: 31 اکتوبر 2021 سید کی عصری مجالس کی روداد گھر آکر سناتے تھے سید کی تفہیم القرآن اور تقریباً ساری کتب گھر پر موجود تھیں۔ ہماری والدہ مرحومہ نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا اور گھر پر بچیوں کو ناظرہ اور ترجمہ قرآن پڑھاتی تھیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو والد و والدہ کو قرآنی مضامین پر مباحث میں مشغول پایا۔ منصورہ مسجد سے دلی لگاو تھا روزانہ مسجد سے گھر آ کر بچوں سے مولانا عبدالمالک حفظہ اللہ کے دروس اور قرآن کلاس کے موضوعات پر گفتگو کرتے اور قرآنی معلومات کے سوالات پر انعام دیتے۔ مبالغے کی حد تک دوسروں کا خیال رکھتے تھے بچوں سے بہت شفقت کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلانے کا شوق تھا ہر سال سردیوں میں اپنے بیٹے کے جمعیت کے دوستوں کی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ہریسہ اور عید قربان کیبعد بونگ نہاری سے تواضع کرتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی عبدالغفور مرحوم سے متاثر ہو کر سید مودودی رح کے مرید بنے۔ عبدالغفور مرحوم نے تقسیم سے قبل پٹھانکوٹ میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور تادم مرگ مقامی جماعت کے امیر رہے(قادیانیوں کے مقابلے میں بنایا جانیوالا اسکول بعد میں گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج کی حیثیت اختیار کر گیا تایا جان کے بڑے بیٹے جاوید مرحوم اس کے پرنسپل بنے، دوسرے نمبر کے بیٹے عبدالشکور بدو ملہی مقامی جماعت کے امیر اور پوتا ذوالقرنین ضلع نارووال یوتھ کا راہنما اور قادیانیوں کیخلاف تحریک کا روح رواں ہے) گھریلو زندگی 1969 میں شادی ہوئی۔ انتہائی تابعدار اور نیک بیوی ملی۔ اور مرحوم خود بھی ارشاد نبوی تم میں سے بہتر وہ ہے ۔۔۔۔کی عملی تصویر تھے۔ زندگی بھر خیر کے کاموں میں تعاون پر مرحوم اہلیہ کا ذکرِ خیر کرتے رہے۔ خاندان اور محلے بھر کے بچوں سے بہت محبت سے پیش آتے۔ نمایاں خوبیاں: عقیدہ توحید ، لین دین میں کھرا پن، انسانیت کی خدمت،مستقل مزاجی۔ جمعیت کے نوجوانوں کو جیل میں کھانا پہنچاتے۔ ان سے محبت و الفت سے پیش آتے۔
مشفق خواجہ کوئی اور نہیں
ادب کی دنیا میں اعتراف (recognition) آج کے ادیب اور شاعر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہم سب اِلَاماشاء اللہ،اسی انسانی کمزوری کا شکار ہیں۔ جو کچھ ہم لکھتے ہیں، اس پر ہمیں داد ملنی چاہیے۔ اگر کتاب چھپے(اور کیوں نہ چھپے بلکہ اگر ہر سال ایک نئی کتاب چھپے توکیا خوب ہے!)فلیپ پر تعریفی کلمات، ایک تحسینی دیباچہ، چند توصیفی تقریظیں۔ پھر اخبارات و رسائل میں کچھ تبصرے، ایک دو شہروں میں بلکہ اگر ہوسکے تو بیرونِ ملک اُردو کی نئی بستیوں میں تقریباتِ اجرائی و رونمائی۔ صاحبِ کتاب کے بارے میں کسی ادبی رسالے کا خاص نمبر یا گوشہ ہی سہی۔ اگر صاحبِ کتاب شاعر ہیں تو ان کا بلند پایۂ کلام ریڈیواور ٹیلی ویژن سے نشر بھی ہونا چاہیے۔ اب صاحبِ کتاب کو، اس کتاب پر کوئی ادبی ایوارڈ بھی ملے اور ”صدارتی تمغائے حسنِ کارکردگی“ کی خواہش تو بالکل فطری ہے۔ مشفق خواجہ ان سب باتوں سے بے نیاز بلکہ نفورتھے۔ خواجہ صاحب ایک مہذّب، مستغنی اور شائستہ انسان تھے۔ انھوں نے اس درجہ اپنی تہذیبِ نفس کرلی تھی کہ وہ ہر طرح کے نام و نمود، جاہ و منصب اور مال و منال کی ہر خواہش سے بے نیاز ہوچکے تھے۔ علّامہ اقبال کا یہ مصرع ان پر صادق آتا ہے: ایّام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر ہماری بعض جامعات میں، زندہ شخصیاتِ ادب پر سندی مقالے لکھوانے کی روایت موجود ہے۔ خواجہ صاحب ہر اعتبار سے اس کا استحقاق رکھتے تھے کہ ان کے علمی و ادبی کارناموں کو موضوعِ مقالہ بنایا جائے، مگر وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ وہ علمی و تحقیقی کام کرنے والوں کی ممکنہ حد تک اور خوش دلی کے ساتھ مدد کرتے،مگر اپنے معاملے میں وہ کسی طرح کا تعاون کرنے سےصاف انکار کردیتے تھے۔۲۰۰۱ء کی بات ہے کہ پروفیسر تحسین فراقی صاحب نے اپنے ایک شاگرد حافظ محمد قاسم (متعلم ایم اے اردو، اورینٹل کالج لاہور) کے تحقیقی مقالے کا موضوع تجویز کیا:”مشفق خواجہ بطور مدوّـن۔“ خواجہ صاحب تک یہ خبر پہنچی تووہ فراقی صاحب سے خفا ہوئے۔ فراقی صاحب نے تو یہ موضوع میرٹ پر تجویز کیا تھااور خواجہ صاحب بہرحال اس کا استحقاق رکھتے تھےمگر خواجہ صاحب کا خیال تھا کہ لوگ اسے ”حقِ دوستی“ پر محمول کریں گے۔ (یہ معلوم ہے کہ خواجہ صاحب، فراقی صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے اور اس مقالے کے نگران اورنگ زیب عالمگیر صاحب سے بھی خواجہ صاحب کو خاص تعلقِ خاطر تھا۔) بایں ہمہ مقالہ نگار نے اپنا کام جاری رکھا۔ ڈاکٹر اورنگ زیب عالمگیر صاحب نے خواجہ صاحب کے برادرِ بزرگ خواجہ عبدالقیوم اور بعض دیگر عزیزوں سے رابطہ قائم کیا تاکہ مقالے کے باب اوّل کے لیے، خواجہ صاحب کے کچھ سوانحی حالات معلوم کیے جائیں۔ خواجہ عبدالقیوم اپنے چھوٹے بھائی کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے انھوں نے ازراہِ احتیاط، معلومات فراہم کرنے سے پہلے ،مشفق خواجہ سے بات کی تو انھوں نے منع کردیا، چنانچہ عالمگیر صاحب اور مقالہ نگار کو، خواجہ صاحب کے سوانحی اور شخصی حالات کے ضمن میں کوئی نئی بات یا مزید معلومات نہ مل سکیں۔ مقالہ بہرحال مکمل ہوگیا، طالب علم کو ڈگری مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد، شعبۂ اردو کے مجلے، بازیافت (مدیر: تحسین فراقی) میں کلیاتِ یگانہ پر مذکورہ طالب علم کا تبصرہ شائع ہوا تو خواجہ صاحب نے پھر تحسین صاحب سے خفگی کا اظہار کیا۔ فی الحقیقت وہ خلوصِ دل سے سمجھتے تھے کہ عالم اور شاعر و ادیب کے لیے شہرت اور نام و نمود مہلک ہے۔ ایک بار راقم الحروف کو خط لکھا:”ہوس، دولت و شہرت کی ہو، نفسِ امّارہ یا کتابوں کی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ الحمدللہ میں ہر معاملے میں قناعت پسند ہوں۔ “ڈاکٹر طاہر مسعود کی روایت ہے:”وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، لہٰذا اصل اہمیت کام کی ہے، نام میں کیا رکھا ہے۔ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہوگا۔ آپ کتنی ہی کوشش کرلیجیے شیطان سے زیادہ مشہور تو نہیں ہوسکتے۔“ (قومی زبان، کراچی، مارچ ۲۰۰۵ء، ص ۲۳) مشفق خواجہ کی شخصیت کا ایک نہایت لائقِ تحسین پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے نیاز مندوں ، اساتذہ اور باصلاحیّت طلبہ کو علمی و ادبی تحقیقی و تنقیدی سرگرمیوں کے لیے آمادہ کرتے، کام کے موضوعات تجویز کرتے۔اور جو جس لائق ہوتا، اسے ویسا ہی کام تجویز کرکے سونپ دیتے۔ کسی کتاب یا مخطوطے کی تدوین کا فیصلہ ہوتا تو خود فوٹو کاپی بنوا کردیتے۔ متعلقہ موضوع پر جس قدر لوازمہ اور مواد ان کی دسترس میں ہوتا، بلاتامّل مہیا کرتے اور جو چیز ان کے پاس نہ ہوتی، اس کی نشان دہی بھی کردیتے۔ راقم اپنی فہم و دانست کے مطابق کسی نہ کسی علمی کام میں مصروف رہتا، مگر جب بھی خواجہ صاحب سے ملاقات ہوتی تو وہ میرے لیے تدوین کا کوئی کام تجویز کردیتے۔ ایک بار اُنھوں نے مجھے جسونت سنگھ پروانہ کا کلیات فوٹو کراکے بھیج دیا کہ اسے مدوّن کردو۔ میں نے معذرت کی کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے کیونکہ مجھے عروض میںمہارت حاصل نہیں اور اس کے بغیر شاعری کی تدوین ناقص ہوگی۔ انھوں نے میری معذرت قبول کرلی۔ اب انھوں نے عبدالرزاق کان پوری کی یاد ایام کا عکس بھیج دیااور ساتھ ہی تدوین اور املا کے سلسلے میں چند ہدایات بھی لکھ بھیجیں۔ اسی طرح خواجہ صاحب نے تحسین فراقی صاحب کے لیے کئی علمی کام تجویز کیے۔ ا ن میں سے کچھ پایۂ تکمیل کو پہنچے، جیسے عجائباتِ فرنگ کی تدوین یا مقالہ:”اردو تنقید کے دس سال“ اور کچھ ناتمام رہ گئے، جیسے: مسیر طالبی کا ترجمہ یا عبرت الغافلین کی تدوین، وغیرہ۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب سے انھوں نے گلشنِ ہمیشہ بہار مرتّب کرایا۔ داکٹر اورنگ زیب عالمگیر صاحب کو وہ خواجہ محمد شفیع دہلوی کی آپ بیتی ریکارڈ کرانے پر اکساتے رہے۔ ایک خط میں انھیں لکھا:”یہ کام بہت اہم ہے۔ اسے آپ دوسرے تمام کاموں ہر ترجیح دیجیے۔ کسی نشست میں ان کے خاندانی حالات ٹیپ کرلیجیے۔ کسی میں دہلی کی ثقافتی زندگی کی تفصیلات، خواجہ صاحب کا وسیع حلقۂ احبا ب تھا۔پہلے ان کے نام پوچھ
ڈاکٹرحسن مرادکی منزل مراد
کرتے۔راقم نےاقبال :سوانح و افکار کے نام سےایک کتاب مرتب کی تو یہ کتاب سلیم منصور خالد صاحب کے توسّط سے یو ایم ٹی نے طبع کی۔ سلیم صاحب راوی ہیں کہ جب یہ کتاب حسن کو دی گئی تورمضان المبارک کی ایک رات سحری تک انھوں نےیہ ساری کتاب ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی۔ سلیم صاحب سے ملاقات پر انھوں نے بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ پانچ سات منٹ تک اقبال اور کتاب کی افادیت پر بات کرتے ہوئے کہاکہ میں اپنی یونی ورسٹی کے ہر طالب علم پر لازم کروں گا کہ وہ اس کتاب کو خریدے اور پڑھے۔چند روز بعد ایک ملاقات میں ڈاکٹر حسن مراد نے یہ بات خود بھی مجھے بتائی۔ دراصل اُنھیں بچپن ہی سے مطالعے کا ذوق و شوق تھا۔ اقبالیات کے حوالے سے بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ عام طور پر کسی بڑے یا انتظامی عہدے پر موجود شخص کے لیے مطالعہ میں اس طرح کا تسلسل رکھنا مشکل ہوجاتا ہےکہ دیگر مصروفیات اور ترجیحات اور ذمہ داریاں آڑے آنے لگتی ہیں، نتیجتاً وہ کتاب سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے مگر ڈاکٹر حسن مراد صاحب کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا۔ انھوں نے بڑے اہتمام اور شوق سے گھر میں بھی ایک ذاتی لائبریری سے قائم رکھی تھی جس سے وہ فارغ اوقات اور تعطیلات میں استفادہ کرتے تھے۔ یوں ان کی کتاب بینی کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ وہ اچھا لکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ترجمان القرآن میں بھی لکھتے تھے۔ اگرچہ بہت تھوڑا لکھا لیکن قلم وقرطاس سے اُن کا تعلق کبھی کمزور نہ ہوا۔ تحریری سرگرمیوں کے لیے وہ روز مرہ کی انتظامی مصروفیات یا ضرورتوں کی وجہ سے وہ لکھنے کے لیے زیادہ وقت نہ نکال پاتے تھے۔ تاہم زندگی کے آخری برسوں میں، معلوم ہوا ،کہ وہ اس جانب توجہ بڑھانے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے۔ اپنی ریکٹر شپ کی ذمہ داری چھوڑنے کے بعد ان کا عزم تھا کہ اب وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ لکھنے لکھانے کا کام کریں گے۔ سلیم منصور خالد صاحب نے تو ان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور برطانیہ جا کرپانچ سال کےلیے یو کے اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کے لیے گوشہ نشین ہو جائیں مگر:” تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ“ ۔ افسوس کہ اس عزم پرعمل پیراہونے کی نوبت نہ آسکی اور وہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ اللہ نے لکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ، ڈاکٹر حسن مراد کو تقریر اور گفتگو کے فن سے بھی خوب نوازا تھا۔ وہ بہترین مقرر تھے۔مجھے کئی بار یو ایم ٹی میں خرم مراد لیکچر سیریز کے مواقع پر ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا۔ وہ سُلجھی ہوئی پُر مغز گفتگو کرتے تھے۔ سامعین اُن کی تقریر سے کچھ حاصل کرکے اُٹھتے تھے۔ ایک بار اُن سے یو ایم ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انھیں تجویز دی کہ یو ایم ٹی میں شعبہ ٔاردو بھی قائم ہونا چاہیے کیوں کہ لاہور میں صرف دو جامعات( پنجاب یونی ورسٹی اور گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی)میں شعبہ ہائے اردو قائم ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ سطح پر لاہور میں کسی اور ادارے میں اردو پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ اگرچہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس ناطے طلبہ و طالبات کو ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے لیکن جامعات میں اس کو ترجیحاً پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے۔اس سے نئی نسل اپنی تاریخ اور ادب کے وسیع اثاثے سے محروم ہو رہی ہے۔ نیز یہ کہ نئے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات میں اردو پڑھنے اور لکھنے کا رجحان کمزور تر ہو رہا ہے۔ پھراسی تناظر میں اقبالیات کے موضوع پر بھی بات ہوتی۔ اقبالیات ،شعبۂ اردو کا اہم جزو ہے۔ جہاں بھی اردو میں ماسٹر ڈگری کرائی جاتی ہے، اقبالیات کو ایک با ضابطہ مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حسن مرادنے شعبۂ اردو کی تجویز کو بہت پسند کیا۔ راقم نے سرگودھا یونی ورسٹی کے ڈاکٹر خالد ندیم صاحب کی ڈاکٹر حسن مراد صاحب سے ملاقات بھی کرائی ۔ وہ بھی کچھ عرصےکے لیے سرگودھا یونی ورسٹی سے چھٹی لے کر آنے پر تیار تھے۔ خود راقم کا بھی ارادہ تھا کہ تدریسی عمل میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن ڈاکٹر حسن صاحب کی مصروفیات آڑے آئیں اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس منصوبے کو عملی شکل نہ دی جا سکی۔ ڈاکٹر حسن مراد کو اﷲ نے فکری اعتبار سے گہرے شعور سے اور عملی اعتبار سے بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اسی سبب وہ آخر وقت تک تحریک ِ اسلامی سے بھی جڑے رہے اور آئی ایل ایم کے نام سے شروع کئے گئے ایک چھوٹے ادارے کو ملک کی ممتاز جامعہ (یو ایم ٹی) تک لانے میں بحسن و خوبی کامیاب ہوئے۔ ایک فرد کے لیے اتنی بڑی کامیابی آسان نہ تھی۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔تحریکوں میں اس طرح کے لوگ اگر پانچ فیصد بھی ہو جائیں تو یہ غنیمت ہوتے ہیں،لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نظر نہیں آتے۔ آج بھی یہی صورت حال ہے کہ ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ تحریکیں خود بھی اپنی ترجیحات کے معاملے میں اِدھر اُدھر ہوجاتی ہیں، کم از کم ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر حسن صہیب مراد کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کے خبط میں مبتلا ہوئے بغیر ایک خوبصورت اور کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی جنتوں کے راہی ہوگئے۔ اللہ ان کی جامعہ کو ان کے فکر و عمل کا بہترین نمونہ بنادے۔ وہ اس چیز کو ہی شعوری طور پر اپنی” منزل مراد “سمجھتے تھے۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ مرحوم سے جو تعارف ان کےجنازے میں ہوا،وہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا ۔ جنازے میں شرکت سے پہلے مجھے ان کے ہردل عزیز ہونےکا اندازہ نہ تھا۔ان کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک دیکھا تو ان کی اس درجہ عظمت اور غیر معمولی شخصیت کا احساس ہوا، حادثے میں انتقال کے
ڈاکٹر محمد ایوب صابر
آسمانِ اقبالیات کا ایک اورستارہ ڈوب گی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی خیابان پشاور کے اقبال نمبر میں ایوب صابر صاحب کا ایک مضمون نظر سے گزرا تھا لیکن بالمشافہہ ملاقات ۱۹۷۷ء کے موسمِ گرما میں جولائی میں ہوئی، تاریخ یاد نہیں ۔ اپریل ۱۹۷۷ء میں اقبالیات پرراقم اور ایوب صابر کے شاگرد، صابر کلوروی کی پہلی کتاب یاد اقبال مکتبہ شاہکار کراچی سے شائع ہوئی،جریدی اشاعت تھی۔صابر کلوروی نے مجھے اپنی کتاب کی تقریبِ رونمائی میں شمولیت کے لیے ایبٹ آباد آنے کی دعوت دی۔میں گورنمنٹ کالج سرگودھا میں لیکچرر تھا۔ ان سے ملاقات نہ تھی۔یہ پہلا رابطہ تھا۔ انھوں نے لکھا کہ آپ مقررہ تاریخ کو ایک بجے تک ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں پہنچ جائیں۔تقریب کی صدارت آپ کریں گے۔راقم مقررہ تاریخ اور وقت پر پہنچا تو کونسل ہال کے دروازے پر لگا تالا منہ چڑا رہا تھا۔میں انتظار میں باغ میں گھومنے لگا۔آدھ گھنٹا، ایک گھنٹا ۔صاحب ِ کتاب ،نہ تقریب ۔وہاں موجود کونسل کا ایک کارندہ بھی لاعلم تھا۔آخر عصر کے وقت تقریب سے مایوس ہو گیا ۔کلوروی کا خط نِکالا ،جس میں یہ لکھا تھا : تقریب کے بعد، آپ دیگر مہمانوں کے ساتھ میرے گاؤںکلور چلیں گے اور ولیمے میں شریک ہوں گے۔شب بسری وہیں ہوگی۔میں نے دو ایک لوگوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کلوراڈّےپر پہنچا جا سکتا ہےمگر وہاں سےگاؤں کلور دو تین میل دور ہے۔پیدل جانا پڑتا ہے ۔رات کے وقت سفر مناسب نہیں ہے۔ راقم نے ایک ہوٹل میں شب بسری کے بعد علی الصبح عزمِ سفر باندھا۔ مانسہرہ کی طرف جانے والی بس میں سوار، کلور اڈّے پر اترا اور گاؤں کا رخ کیا ۔خدا بھلا کرے کلور کےایک شخص کا جو مجھے ساتھ لے چلااور صابر صاحب کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ صابر !باہر نکلو، مہمان آئے ہیں ۔ صابر نکلے تو انھوں نے مجھے اور میں نے انھیں دیکھا۔ گھر کے اندر لے گئے،والد سے تعارف کرایا، وہ بھی بہت خوش ہوئے ۔پتا چلا رات ولیمے میں آئے ہوئے مہمان ناشتا کرکے جا چکے تھے۔ جانے والوں میں ایوب صابر اور رحیم بخش شاہین شامل تھے۔خود صابر کلوروی سسرال جانے کے لیے تیّار بیٹھے تھے۔بہر حال انھوں نے ناشتا بنوایا ، گفتگو ہونے لگی ۔عذر معذرت کرنے لگے کہ تقریبِ رونمائی کا پروگرام منسوخ ہو گیا تھا اور وقت نہ تھا کہ آپ کو اطلاع دی جاتی۔ خیر ،ناشتا کرکے ہم گھر سے اکٹھے نکلے۔کلور کے اڈّے پر پہنچ کر راقم ایبٹ آباد کی بس میں بیٹھا اور صابر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ دوسری سمت میں روانہ ہو گئے۔صابر صاحب نے مجھے ایوب صابر کے مکان کا پتا بخوبی سمجھا دیا تھا۔ جب میں نے ان کے مکان پر دستک دی تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو نام بتایا۔میری ان سے اور ان کی مجھ سے پہلی ملاقات تھی۔ اتفاق سے مرحوم رحیم بخش شاہین بھی ان کے ہاں موجود تھے۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔آخری ملاقات ستمبر ۲۰۲۲ء میںاسلام آباد میں ان کے مکان پر ہوئی۔۴۵ برسوں کی کہانی بہت لمبی ہے، فقط چند جھلکیاں پیش کرنا ممکن ہے۔ اقبال پر ان کے چند مضامین دیکھ چکا تھا۔اسی پہلی ملاقات میں نے انھیں اقبالیات کے بعض موضوعات پر لکھنے پر متوجہ کیا بلکہ اُکسایا۔ کہنے لگے: میں نے دو تین مضامین اور بھی لکھ رکھے ہیں اور کچھ مزید بھی لکھوں گا، کتاب تیار کرنے کا ارادہ ہے۔ راقم نے کہا: مزید ضرور لکھیے اور جو لکھ رکھے ہیں انھیں چھپوا بھی دیجیے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ پشاور یونی ورسٹی کی متعلمی کے زمانے میں مضمون نویسی کے مقابلوں میں ایک بار اوّل ، دوسری بار دوم انعام جیت کر اپنے استاد اور اقبال شناس پروفیسر محمد طاہر فاروقی سے داد ِتحسین حاصل کر چکے تھے۔یونی ورسٹی آنے سے پہلے ایبٹ آباد کالج میں انھیں ایک بڑے قابل استاد پروفیسر صغیر احمد جان دہلوی سے بھی اکتساب کا موقع ملاتھا۔اس زمانے میں شعر وادب کے لیے کالج کی فضا بہت سازگار تھی۔ ذکر تھاان کے مکان پر پہلی ملاقات کا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد کچھ وقفہ آیا۔ راقم کا سرگودھا سے لاہورگورنمنٹ کالج تبادلہ ہو گیا۔پونے دو برس بعد یونی ورسٹی اورینٹل کالج سے بطور لیکچرر شعبۂ اردو سے وابستہ ہوا۔اس زمانے میں راقم تعطیلات میں چند دنوں یا ہفتوں کے لیے ایبٹ آباد چلا جاتا۔ ایوب صابر صاحب سے ملاقات رہتی۔ وہ ایبٹ آباد کالج میں پڑھا رہے تھے۔ملاقات میں قدرتی طور پر اس طرح کی گفتگو ہوتی: ”کیا کر رہے ہیں آج کل؟“ ”زیادہ تر مطالعہ۔“ ”کچھ لکھ بھی رہے ہیں ؟“ ”جی ہاں ۔“ ”اقبال کی طرف آئیے۔ساتھ ہی کچھ لکھیے بھی۔“ نتیجہ: ایوب صاحب نے علّامہ اقبال اوپن یو نی ورسٹی کی ایم فل کلاس میں داخلہ لےلیا ۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا: اقبال پر بعض معاندانہ کتب کا جائزہ۔ راقم کو اس کے بیرونی ممتحن اور زبانی امتحان لینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ ایم فل تو۱۹۸۸ء میں مکمل ہو گیا ۔نظر ثانی کے بعد اسے اقبال دشمنی: ایک مطالعہ کے عنوان سے۱۹۹۳ میں ڈاکٹر جاوید اقبال اور راقم کے دیباچوں کے ساتھ شائع کرادیا۔ صابر کلواری خود تو ڈاکٹریٹ کی منزل سر کر چکے تھے، وہ اپنے استاد ایوب صابر کو بھی مسلسل اکساتے رہتے تھے اور راقم بھی انھیں توجہ دلاتا رہا۔ آخر کار، قدرے توقف کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ انھوں نے ۱۹۹۵ء میں ۴ برس قبل از وقت ، ریٹائرمنٹ لےلی ،کیوں؟(اس کا جواب آگے آتا ہے۔) وہ پنجاب یونی ورسٹی میں پی ایچ ڈی کےلیے رجسٹریشن کر اچکے تھے اور اب بالکل یکسو ہو کر کام کرنا چاہتے تھے۔ مقالے کےلیے باہمی مشورے سے علّامہ اقبال کی شخصیت اور فکر و فن پر اعتراضات :تحقیقی و تنقیدی جائزہکا عنوان طے ہوا ۔ راقم ان کا نگران مقرر ہوا ۔ اس زمانےمیں، جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، راقم تعطیلات میں کچھ دنوںکےلیے ایبٹ آباد جایا کرتا تھا ۔ایوب صاحب سے ملاقات ہوتی اور تبادلۂ خیال بھی۔ ڈیڑھ دو برس تو وہ صرف کتابوں کی جمع آوری اور مطالعے میں مصروف رہے ۔ میں نے اپنےتجربے کی بنیاد پر انھیں مشورہ دیا کہ وہ لکھنے کاکام بھی شروع کردیں۔انھیں خود بھی یہی احساس ہوا کہ مطالعے کو لمبا کرنے سے لکھنے
معلّم،محقّق اور قلم کارانور محمود خالد
۲۲ نومبر ۲۰۲۱ء بروز پیر، ابھی سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے کہ مجھے واٹس ایپ پر اپنے دوست (اور متعدّد کتابوں کی تالیف و تدوین میں راقم کے ساتھ شریک) پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب کا یہ پیغام موصول ہوا:”سیرت نگاری کا درخشاں باب بند ہوگیا۔ ڈاکٹر انور محمود خالد صاحب وفات پاگئے۔ اِنَّا لِلَّہِ وَاِنَّا اِلَیْہ ِ رَاجِعُوْنَ۔ اردو نثر میں سیرتِ رسول ﷺ اُن کا شاہکار اور شفاعت کی دستاویزتھا، ان شاء اللہ۔“ انور محمود کتنے خوش بخت ہیں کہ بلاشبہہ وہ سکندر کی طرح خالی ہاتھ نہیں ،بلکہ اپنی ”شفاعت کی دستاویز“لے کر رخصت ہوئے۔ خدا کرے اگلی دنیا میں یہ دستاویز اُن کے لیے مختلف مراحل سے بلاروک ٹوک گزرنے کا ”ویزا“ ثابت ہو۔اور باری تعالیٰ کے دربارسے اُمیدِ واثق ہے کہ ایسا ہی ہو گا ،اِن شاءاللہ۔ ستّرکی دہائی میں(سنہ یاد نہیں)مقامی حلقہ اربابِ ذوق نے محفل ہوٹل لائل پور (اب:فیصل آباد) میں خورشید رضوی کے ساتھ ایک شام منانے کا فیصلہ کیا۔ پروفیسر ریاض مجید اور انور محمود خالد، اس تقریب کے مہتمم تھے۔ راقم، خورشید رضو ی اور جناب انور سدید سرگودھاسے چلے۔ بعد عصر تقریب شروع ہوئی۔ خورشید رضوی صاحب کی شخصیت اور شاعری پر مضامین پڑھے گئے اور آخر میں مشاعرہ ۔خالد صاحب سےغائبانہ تعارف تو ۱۹۶۸ءسے تھا، جب وہ نعیم صدیقی صاحب کے سیـارہ میں معاون مدیر کے طور پر کام کرہے تھے۔ (ان کے بعد راقم معاون مدیر مقرر ہوا۔ ) لیکن بالمشافہہ یہ پہلی ملاقات تھی۔غالباً اسی موقعے پراُنھوں نے راقم کو دستخطوں کے ساتھ اپنی شاعری کی پہلی کتاب عہد نامہ پیش کی۔ میں نے اس پر ایک مختصر سا تبصرہ بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد بارہا ملاقاتیں ہوئیں۔ کئی بار وہ سرگودھا آئے، اور ڈاکٹر وزیر آغا کے ہاں ، انور سدید، خورشید رضوی، پروفیسر غلام جیلانی اصغر اور سجاد نقوی کے ساتھ اُن سے صحبت رہی۔بالعموم پروفیسر ریاض مجید بھی اُن کے ساتھ ہوتے۔ ڈاکٹر سیـّد معین الرحمان مرحوم،غالباً ۱۹۷۴ء میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لائل پور کے صدر ِشعبۂ اُردوہو کر لائل پور پہنچے۔ خالد صاحب اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ معین صاحب نے اُنھیں توجّہ دلائی کہ پی ایچ ڈی کر لیجیے۔معین صاحب کی بڑی خوبی تھی کہ وہ متعلقین کو اپنی استعداد بڑھانے کی طرف متوجہ کرتے، بلکہ مسلسل اُکساتے۔ ان کی توجہ سےنہ صرف انور محمود خالدبلکہ ریاض مجید، ریاض احمد ریاض،رشید احمد گوریجہ اورافضال احمد انورنےبھی آگے پیچھے پنجاب یونی ورسٹی سے پی ایچ ڈی کرلیا۔ انور محمود نےاُردو نثرمیں سیرتِ رسول کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرلی۔ میرے استاد ڈاکٹر وحید قریشی مرحوم غالبا اُس زمانے میں اقبال اکادمی کے ناظم تھے۔ اُنھوں نےخالد صاحب سے مقالہ لے کر۱۹۸۹ء میں شائع کردیا۔خالد صاحب کا خیال تھا کہ وہ اِسے اَپ ڈیٹ کریں گے۔ سیرتِ رسول ﷺ ایک سدا بہار موضوع ہے۔ اس پر ہر سال کتابوں کا اضافہ ہوتاتھا، اب بھی ہوتا ہے۔خالد صاحب آخری زمانے تک نئی کتابیں جمع کرتے رہے۔ دوست کہتے رہے کہ جو کچھ لوازمہ میسر آگیا ہے۔ اسی کی مدد سے کتاب کادوسرا حصہ لکھ ڈالیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب راقم کتابیاتِ اقبال کےلیے حوالے جمع کررہا تھا تو لائل پور گیاخالدصاحب سے ملاقات کے لیے، اُن کے گھر پہنچا،اقبالیاتی کتابوں کے حوالے نوٹ کیے۔( اُن دنوں وہ کرائے کے مکا ن میں مقیم تھے۔) راقم نے اس ملاقات میںبھی مشورہ دیا کہ دوسرا حصہ لکھنا شروع کیجیے۔ لیکن پھر وہ تعمیرِ مکان میں مصروف ہوگئے۔ یوں دوسرا حصہ نہ لکھا جا سکا۔ انور محمود خالد اعلیٰ درجے کا علمی و ادبی اور شعری ذوق رکھتے تھےاور منجھے ہوئے قلم کار تھے۔جیسی اُن کی صلاحیت تھی، اس کے مطابق اُنھوں نے تصنیف و تالیف کی طرف خاطر خواہ توجّہ نہیں دی، پھر بھی وقتاً فوقتاً جو کچھ لکھّا، وہ رسائل میں بکھرا ہوا ہے۔ مثلاً الحمرا ہی میں اُن کے حسبِ ذیل مضامین شائع ہوئے: – علّامہ اقبال بحیثیت نعت گو اپریل ۲۰۰۷ء ۲- تصوراتِ عشق و خرد، اقبال کی نظر میں جون ۲۰۰۹ء ۳- اقبال ، مشاہیرِ کشمیر اور جگن ناتھ آزاد ستمبر ۲۰۰۹ء ۴- فکرِ اقبال اور عصرِ حاضر جولائی ۲۰۱۰ء ۵- بانی پاکستان کے نام، مفکّرِ پاکستان کے خطوط اکتوبر ۲۰۱۵ء ۶- ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کی پہلی برسی پر نومبر ۲۰۱۶ء ۷- غلطی ہائے مضامین مت پوچھ! مئی ۲۰۱۷ء ۸- جسٹس (ر) ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کی دوسری برسی پر نومبر ۲۰۱۷ء ۹- عبدالوہاب خان سلیم مرحوم کی یاد میں جنوری ۲۰۱۸ء ۱۰- علامہ اقبال اور آفتا ب اقبال پر ایک طائرانہ نظر مئی ۲۰۱۹ء ۱۱- ”۔۔۔۔یہ اندازِ گفتگو کیا ہے؟“ اگست ۲۰۱۹ء ۱۲- ماہنامہ الحمرا کا گوشۂ کشمیر اکتوبر ۲۰۱۹ء ۱۳- ”غنچہ لگا پھر کھلنے۔۔“(جگن ناتھ آزادکی کتاب اقبال اور کشمیر کے حوالے سے چند معروضات) نومبر ۲۰۱۹ء ۱۴- ایس اے واحد ، وادیِ لولاب کے انور شاہ کشمیری اور کشمیر کے زندہ دل برہمن زادے کون؟ (چند تصریحات-ڈاکٹراسلم انصاری کے مضمون کے جواب میں ) فروری ۲۰۲۰ء ۱۵- دو اہم ادبی شخصیات کی رحلت جولائی ۲۰۲۰ء ایک زمانے میں خالد صاحب نے رسالہ فنون میں علامہ اقبال کی نظموں ”شکوہ“ اور ”جوابِ شکوہ “ پر دو مفصل مضمون شائع کیے تھے۔ان مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کی زیادہ توجہ اقبالیات پررہی۔یقیناً وہ ایک جیـد اقبال شناس بھی تھے۔ اگر اُن کے جملہ مضامین تلاش اور جمع کیے جائیں تو ایک نہایت معقول تحقیقی اور تنقیدی مجموعہ تیار ہوجائے گا۔ جسٹس (ر)ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے نام مشاہیرِ عالم کے خطوں کا ایک اُردو اور ایک انگریزی مجموعہ شائع کیا تھا۔اُردو مجموعہ خطوط بنام جاوید اقبال کے عنوان سے ۲۰۱۱ء میں طبع ہوا۔جاوید صاحب ۲۰۱۵ء میں فوت ہو گئے۔مذکورہ بالا اُردو مجموعے کی اشاعت کے بعد اُنھیں جو خطوط موصول ہوئے، وہ اُنھیں ایک فائل میں محفوظ کرتے گئے۔ خالدصاحب نےالحمرا میںشائع شدہ اپنے ایک مضمون میں اِن خطوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:”ڈاکٹر جاوید اقبال کے ورثا سے گزارش ہے کہ اِن چھے برسوں کے موصولہ خطوط کی فائل ڈھونڈیں اور اُنھیں مرتّب کر کے سپردِ اشاعت کریں۔“۔۔۔۔خالد صاحب خط نویسی میں بڑے مستعد تھے۔بیسیوں
امجد اسلام امجد
اورینٹل کالج میں امجد اسلام ایک کلاس مجھ سے پیچھے تھے۔ میرا سیشن ۱۹۶۴ء-۱۹۶۶ء کا تھا، اور اُن کا ۱۹۶۵ء-۱۹۶۷ء ۔ یونی ورسٹی کے طلبہ میگزینمحّور کی ادارت میں بھی یہی صورت تھی۔راقم میگزین بورڈ کا چیئر مین اورمحّور کا چیف ایڈیٹر منتخب ہوا۔اگلے برسمحّور امجد اسلام کی ادارت میں شائع ہوا۔ جب وہ سالِ اوّل میں داخل ہوئے، غالباً ستمبر ۱۹۶۵ء میں۔ یونی ورسٹی کے اندر اور بیرونی کالجوں میں بھی ہونے والے مشاعروں میں شعبۂ اُردو اور اورینٹل کالج کی نمائندگی کرنے لگے۔ بعض اوقات شاعری کے انعامی مقابلوں میں اوّل یا دوّم انعام بھی لے آتے۔ راقم نے ۱۹۶۷ء-۱۹۶۹ء کا زمانہ متفرق مصروفیات میں گزارا۔(میونسپل ڈگری کالج چشتیاں، ایف سی کالج لاہور، ہفت روزہ آئین لاہور ،ماہ نامہ سیّارہ لاہور، ماہ نامہ اُردو ڈائجسٹ لاہور)چونکہ زیادہ تر لاہور میں رہا، اس لیے اِس عرصے میں وقتاً فوقتاً ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ایم اے او کالج میں لیکچرر ہو گئے تھے۔ اُس زمانے میں وہ فلیمنگ روڈ پر رہتے تھے۔ اُن کے بالمقابل مکان میں میرے دوست حفیظ الرحمٰن احسن مقیم تھے۔ کبھی کبھی اُن کے ہاں جاتا ، تو امجد سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ وہ چائے پلاتے اور شاعری بھی سناتے۔ فلیمنگ روڈ پر ہی پروفیسر آقا بیدار بخت رہتے تھے۔ وہ شاعری میں امجد کے استاد تھےاور کرکٹ میں بھی۔ آقا صاحب امجد کے ساتھ خود بھی کرکٹ کھیلا کرتے۔ آقا بیدار بخت بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے۔ ایک اعتبار سے وہ امجد اسلام کےمحسن تھے۔ آقاصاحب نے دارالعلوم شرقیہ کے نام سے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں میں بی اے کا امتحان پرائیویٹ طور پر نہیں ہوتا تھا۔ پہلے عربی، فارسی اور پنجابی میں سے کسی ایک زبان پاس کرنا پڑتا ، پھر انگریزی اونلی کا، پھر آپ آگے بڑھ سکتے تھے۔ اسے “وایا بٹھنڈا” کہتے تھے۔ آقا صاحب نے اس راستے سے سینکڑوں نوجوانوں کو سو ل سروس میں بھیجا۔ امجد اسلام امجد کومطالعے سے دلچسپی تھی، آقا صاحب اُسے پڑھنےکے لیےاسےکتابیں دیتے اور کہتے:لے جاؤ اور پڑھو۔ آقا صاحب کو خدا جنّت نصیب کرے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تحریکِ آزادیِ کشمیر کے مجاہد سیّد علی گیلانی حصولِ تعلیم کےلیے سری نگر سے لاہور آئے تھے۔ آقا صاحب کے ادارے میں داخل ہوگئے۔ آقا صاحب نے اندازہ لگایا ہوگا کہ با صلاحیّت لڑکا ہے۔ گیلانی مرحوم لکھتے ہیں: انھوں نے بغیر فیس لیے مجھے ادیب عالم میں داخلہ دے دیا حالاں کہ ابتدائی درجہ ادیب تھا۔ آقا صاحب نے علی گیلانی کو کلاسیکی شاعری پڑھائی۔وہ آقا صاحب کے مدّاح تھے۔بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صاحب ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔امجد اسلام نے ان سے یہ بات سیکھی اور اسے آگے منتقل کر دیا،مثلاً:امجد نے اوریا مقبول جان کو ڈرامانگاری پر لگا دیا۔ امجد اسلام امجد اصلاً شاعر تھے۔ یوں تو انھوں نے بہت سی اصنافِ شعر میں طبع آزمائی کی، مگر راقم کے خیال میں وہ نظم کے شاعر تھے اور نظم بھی آزاد۔ اگرچہ انھوں نے ایک بڑا ذخیرہ غزل کا بھی یادگار چھوڑا ہے۔ امجد ،زمانہ طالب علمی میں مقبول تھےاورآخری زمانے تک ان کی مقبولیت ،نہ صرف برقرار رہی ،بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا۔حالانکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ان کی شخصیت اور شاعری میں کچھ ایسی کشش تھی کہ کوئی محفل ،کوئی مشاعرہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ امجد اسلام کی ایک حیثیت ڈراما نگار کی تھی ، اُن کے ڈراموں (وارث۔سمندر ) کی مقبولیت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ ڈراما نگار تھے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص درجۂ اوّل کا شاعر ہو اور ساتھ ہی درجۂ اوّل کا ڈراما نگار بھی۔ (راقم نے اُن کے افسانے بہت کم پڑھے، نہ پڑھنے کے برابر، اس لیے اُن پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔) ۱۹۷۴ء میں راقم نے ایک کتاب مرتّب کی: اصنافِ ادب۔ اِس میں ہر صنف کا تعارف کرانے کے بعد اُس کے نئے پرانے نمونے دیے گئے تھے۔عنوان “نعت” کےتحت نئی پرانی نعتوں کے کچھ نمونے تھے۔ آزاد نعت کے نمونے کے طور پرمیں نے امجد اسلام کی حسبِ ذیل نعت شامل کی۔ (جو مجھے بہت پسند تھی اور آج بھی ہے): اَبر،خورشید،قمر روشنی،پھول،صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا کوئی بھی چیز،کوئی چیز نہ تھی سِرِّ مخفی تھا خدا کوئی تخلیق نہ تھی حرفِ اقرار نہ تھا مہرِ توثیق نہ تھی سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی آپؐ نے سردعناصر کو حرارت بخشی آپ نے،صلِ ّ علیٰ اَبر،خورشید،قمر روشنی،پھول،صدا سب کو مفہوم دیا حاجتِ کون و مکاں ،مقصد خلقِ بشر مجھ پہ بھی ایک نظر مجھ کو بھی دیجے کبھی میرے ہونے کا پتا یا نبی !صلّ ِعلیٰ یا نبی! صلِّ علیٰ میراخیال ہے کہ اگر اردو نعتوں کا ایک کڑا انتخاب کیا جائے تو امجد کی یہ نعت اس میں جگہ پائے گی۔ ایک بلند پایہ شاعر اورڈرامانگار اورایک بہت اچھا انسان ہم سے رخصت ہو گیا ۔بڑی محرومی ہے ۔باری تعالیٰ اسے بخشے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے،آمین یا ربّ العالمین۔ 18 فروری 2023ء