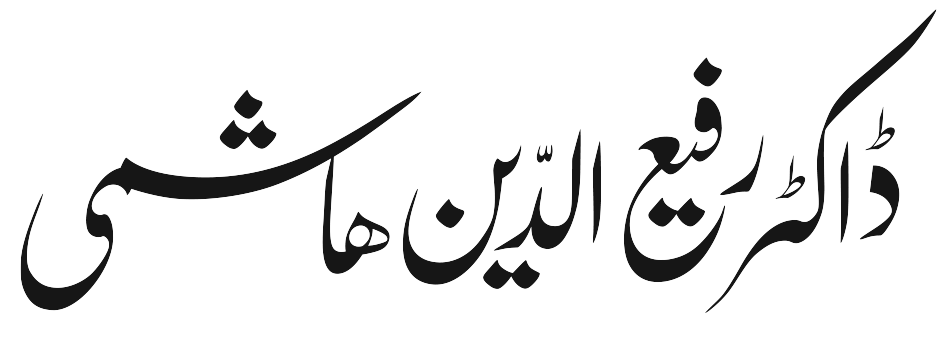(بھارت کا ایک سفر)
میری عمر کے پاکستانیوں نے جب ہوش سنبھالا اور برعظیم کی تاریخ کا مطالعہ کیاتوعمر کے ساتھ، جوں جوں مطالعہ وسیع ہوتاگیا،بھارت میں مسلم آثار کو دیکھنے کا شوق بھی بڑھتاگیا کیوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر اپنے سیکڑوں سالہ دورِ حکومت میں یہاں کے چپے چپے پر اپنی تہذیب وثقافت اورحکمرانی کے نقوش ثبت کیے۔ قلعے،مسجدیں،مقبرے،مزار، محلات، عمارات، کنویں اورباولیاں،سڑکیں اورشاہراہیں،پھررسوم ورواج،ادب وآداب، طوراطوار، لباس اور پوشاک، کھیل اورتماشے، میلے ٹھیلے۔ غرض زندگی کاکوئی شعبہ ایسا نہیں جو اب بھی مسلمانوں کے اثرات سے خالی ہو۔ انگریزوں نے دلّی پرقبضہ مستحکم ہونے کے بعد مسلم عہد حکومت کی بہت سی عمارتوں،مسجدوں اور مقبروں کو گرا دیا، اس کے باوجود دلّی میں اب بھی مختلف ادوار کی چھوٹی بڑی بیسیوں بلکہ شاید سیکڑوں یادگاریں باقی ہیں۔ (گو،موجودہ بھارتی حکومت کی اشیر باد سے بعض لوگ اورپارٹیاں بابری مسجد کے انہدام کے بعد باقی آثار اور یادگاروں کو بھی مٹانے کے در پے ہیں۔ )
لیکن مجھ ایسوں کے لیے بھارت کے سفر میں طرح طرح کی رکاوٹیں اورمجبوریاں حائل رہیںاور۱۹۶۵ء کی جنگ کے بعد اُن پابندیوں میں مزید اِضافہ ہوتاگیا۔
کئی سال بعد۱۹۸۶ء میں اقبال اکیڈمی حیدرآباد دکن کی طرف سے عالمی اقبال سیمی نار میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ اس پہلے دعوت نامے کے بعد، ایک ایک دو دو سال وقفوں سے ادبی کانفرنسوں اورسیمی ناروں کے دعوت نامے ملنے لگے۔ ۱۹۸۶ء سے اب تک تیس اکتیس برسوں میں تقریباً تیس دعوت نامے ملے ہوں گے جو مختلف شہروں سے تھے۔ دہلی، علی گڑھ،احمدآباد، حیدرآباد، پٹنہ، کلکتہ، بنگلور، رائے بریلی،اعظم گڑھ اورلکھنؤمگر افسوس ہے کہ میں صرف دوبار بھارت جاسکا۔ اور ان دوسفروں میں بھی صرف تین ہی شہروں (دہلی، حیدرآباداوربھوپال) کی زیارت کرسکا۔ سب سے زیادہ قلق سری نگر نہ جاسکنے کا ہے۔
سری نگر کے ذکر سے تصور میں کشمیر کی وادیوں ،کوہساروں اور جھیلوں کی تصویریں بننے لگتی ہیں اور اقبال کا یہ شعر ذہن میں گونجنے لگتا ہے :
پانی ترے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب
مرغانِ سحر تیری فضائوں میں ہیں بے تاب
دراصل نادیدہ کے تصور میں بھی ایک رومان ہوتا ہے۔’’ آتش چنار‘‘ کا نظارہ تو ہم نے ایبٹ آباد میں کیا اور باربار کیا۔(یہ کئی سال پہلے کی بات ہے)مگر’’ وادیِ لولاب‘‘ کیسی ہو گی۔۔۔۔۔۔؟شاید شمالی علاقہ جات کے بعض مناظر کی طرح۔۔۔۔۔۔۔،مگر نہیں، ان سے فزدں تر۔علامہ اقبال کو فقط ایک ہی بار کشمیر جانا نصیب ہوا مگر ان کی ساری عمر کشمیر کو’’کسی بہانے تمھیں یاد کرنے لگتے ہیں ‘‘کی کیفیت میں گزری ۔کلامِ اقبال کوپڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حینِ حیات کسی نہ کسی عنوان یا کسی نہ کسی حوالے سے(سا قی نامہ۔کشمیر۔غنی کاشمیری۔ملا ضیغم لو لابی کی بیاض۔ آبِ ولر۔آتشِ چنار ۔وادیِ لو لاب۔ایرانِ صغیر ۔سیاہ چشمانِ کشمیری۔پیرکِ اندرابی ۔ولر کے کنارے ۔خطّۂ گل) وہ کشمیر کو یاد کرتے رہے۔
اقبال اکیڈمی کے مذکورہ بین الاقوامی سیمی نار میں سات حضرات(ڈاکٹر جاوید اقبال ،پروفیسرمرزامحمدمنور،ڈاکٹر جمیل جالبی،عبدالرؤف عروج،انتظار حسین،ڈاکٹر معین الدین عقیل اور راقم) مدّعو تھے مگر صرف عقیل صاحب اور راقم ہی شریک ہو سکے البتہ اقبال کاسیاسی کارنامہ کے مصنف محمد احمد خاں اورمعروف سیرت نگار مصباح الدین شکیل صاحبان اپنے طور پر حیدر آباد گئے تھے اور سیمی نار میں شریک ہوئے۔
۱۵؍اپریل۱۹۶۸ء :میں تقریباً نو بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پُرہجوم اور افراتفری ۔ مسافر زیادہ ،جگہ کم۔برادرم تحسین فراقی اپنے ایک دوست فاضل صاحب کو ساتھ لائے تھے۔ان کی وساطت سے امیگریشن اور کسٹم کے مراحل آسان۔ پاسپورٹ پر Exitکی مہرلگنے کے بعد،میں ریل کے درجۂ اوّل میں بیٹھ گیا۔ سامان ایک درمیانے سے اٹیچی اور کتابوں کے دوکارٹنوں پرمشتمل تھا۔ ساڑھے گیارہ بجے مسافر آنابند ہوگئے۔لوگ مع سامان بہت آچکے تھے۔ بچے اور بچیاں ،جوان اوربوڑھے،باپردہ خواتین( بعض صرف بادوپٹہ) ،ان کے ساتھ چھوٹے بڑے اٹیچی، گٹھڑیاں بلکہ بڑے بڑے گٹھڑ اور ساتھ ہی چیخ پکار ،شوروغوغا،بہت ذہنی کوفت ہوئی۔ ٹی ٹی نے ازراہِ کرم مجھے متصل کوپے میں بٹھا دیا جو کسی سابق ریلوے افسر کے لیے مخصوص تھا۔اس میں کل پانچ افراد تھے۔ریل تقریباً ایک بجے روانہ ہوئی اورتین چار گھنٹے کایہ عرصہ اخبارات و رسائل پڑھنے، اونگھنے اور جمائیاں لینے(رات دیر سے سویا تھا اور صبح بہت جلد اٹھ گیا۔ سفر میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے) اورپلیٹ فارم پرآنے والے مسافروں کے مشاہدے میں گزرا۔
ریل،لاہور ریلوے اسٹیشن سے چلی توواہگہ سے آگے دائیںبائیں درختوں کے جھنڈ اورپکی ہوئی گندم کے سنہری کھیت دور تک چلے گئے تھے۔ ایک جگہ کھیتوں میںسُؤروں کے ریوڑ نظر پڑے۔ریلوے افسر کی بیوی نے منہ بنا کر ناک کے آگے پلّو رکھ لیا۔ پتا ہی نہیں چلاکہ ہم حدودِوطن سے نکل کر بھارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ تقریباً ایک گھنٹے میں ریل گاڑی اٹاری جاکھڑی ہوئی۔
بھارت کا یہ پہلا سفر تھا مگر بھارتی سرزمین پر،میں دوسری بار قدم رکھ رہاتھا۔
یہ الگ قصہ ہے:مختصر یہ کہ۱۹۶۵ء کی سترہ روزہ جنگ کے بعدجنگ بندی (ceasefire)ہوئی توبھارتی قصبہ کھیم کرن(بعض روایات کے مطابق مولاناابوالکلام آزادکی ولادت اسی قصبے میں ہوئی،مگراُن کے مدّاحین اس کی تردید کرتے ہیں۔) پاکستانی فوج کے زیرِ قبضہ تھا۔ ہمیں وہاں جانے اور گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔اب اٹاری اترتے ہوئے،گویامیں بھارت کی سرزمین پردوسری بارقدم رکھ رہاتھا۔حکم ہوا:مسافر،ریل سے سامان اتار کرپلیٹ فارم پررکھ دیں،ریل خالی کردیں۔
دلّی سے لاہور آنے والی ریل ابھی نہیں پہنچی تھی۔
لمبی لمبی قطاریں ۔پہلے گیٹ پاس،پھر نمبر لگا،پھر ہیلتھ کی مہر،ناواقفوں سے ۵،۱۰ روپے ہتھیا لیے۔ایک جگہ پاسپورٹ کا اندراج ،۲۰ روپے رکھوا لیے۔یہ سب’’ غیر سرکاری‘‘ فنڈ۔
ایک سردار جی سامان کی پڑتال کر رہے تھے۔ قطارمیں لگا،باری آئی تو کتابوں کے ڈبّے میز پر ان کے سامنے رکھ دیے ۔
’’کیہ اے ایِناں وچ؟‘‘
’’کتاباں۔‘‘
’’اچھا،کھولو،وِکھائو۔‘‘
وِیکھ کر کہنے لگے :’’اینیاں کتاباں؟‘‘
میں نے کہا :’’دوستاں لئی لے جا ریا واں،تحفہ تحائف اے ‘‘
کچھ ردو قدح کے بعد کتابیں ’’پاس ‘‘ہو گئیں ۔
مجھے مشفق خواجہ یاد آگئے ہیں ۔ شاید ۱۹۸۷ء میں مشفق خواجہ اور ان کی بیگم بھارت کے دورے پر گئے۔تاریخی آثار دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں بھی جمع کرتے رہے۔کچھ تحفے میں ملیں بہت سی خریدیں۔تقریبادس بارہ بوریاں کتابوں کی بن گئیں۔اب یہ پاکستان لے جائیں تو کیسے؟ہوائی جہاز میں تو ہزاروں روپے خرچ ہو ں گے۔فکر مند تھے مگر ڈاکٹر خلیق انجم نے انھیں اطمینان دلایا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔وہ خواجہ صاحب کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ دہلی کے اندرا گاندھی ہوائی اڈے پر گئے۔
سامان کے کائونٹر پر ایک سردار جی براجمان تھے۔وہ بوریوں پر معترض ہوئے۔خلیق انجم نے ذراسے جھک کر ان کے کان میں کہا :’’آپ کو پتا نہیں یہ پاکستان کے بہت بڑے صحافی اور لکھاری ہیں ۔خالصتان تحریک کی حمایت میں مسلسل لکھتے رہتے ہیں ۔‘‘یہ سننا تھا کہ سردار جی نے کہا :’’جائو ، جائو۔لے جائو ،لے جائو۔‘‘
ساڑھے تین بج گئے،بھوک لگ رہی تھی۔سوا تنتراکمارپوریاں تل رہا تھا۔چائے بھی میسر تھی مگرسو اتنترا کمار کی بنائی ہوئی پوریاں کھانے کو جی نہ چاہا۔چنانچہ بسکٹ اور چنوں پر گزارا کیا جو مسافر نے گھر سے نکلتے وقت ازراہِ احتیاط بیگ میں رکھ لیے تھے۔
پلیٹ فارم پر ’’کرنسی تبدیل ‘‘کے کئی کائونٹر نظر آئے۔سو روپے کے ۸۵ بھارتی روپے ۔بعد میں پتا چلاکہ سوکے سو ملنے چاہییں تھے۔(پھر غچہ دے گئے،پہلے ریڈکلف ایوارڈ کے ذریعے، پھر اقوامِ متحدہ میں پنڈت نہرو کی دُہائی اور جھوٹے وعدے کے ذریعے ، کہ ہم کشمیر میں استصواب کرائیں گے، اور پھر معاہدئہ تاشقند کے ذریعے)۔
دو خط لکھے تھے کہ دہلی سے ریل آ گئی ۔خط لاہور جانے والے ایک پاکستانی کو دیے کہ لاہور جا کر پوسٹ کر دیں ۔شام چھے بجے دہلی والی ریل میں بیٹھ گیا۔اٹاری تا دہلی درجہ اول کا ٹکٹ ۱۸۰ روپے۔قلی پچیس روپے ۔ریل پتا نہیں کب چلے گی؟ساڑھے نو بجے اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا ۔دو گھنٹے بعد ریل چل پڑی ۔رات بھر جاگتا سوتا رہا ۔امبالے رکی ،فجر کا وقت تھا۔ریل کا غسل خانہ ہماری ریلوں کے غسل خانوں سے کشادہ۔نمازِ فجر،تلاوت۔۔۔مشاہدہ کرنے لگا ۔کرنال ،کورو کشتیر،پانی پت(حالی یاد آئے)،سونی پت۔ریل تقریباً ساڑھے دس بجے دہلی کے ریلوے سٹیشن میں داخل ہوئی۔
پرانی دہلی کا سمیر ہوٹل ،بلّی ماراں ،کرایہ: ایک شب و روز پچاس روپے۔۱۶ ؍ اور ۱۷؍اپریل کو دلّی میں کچھ دوستوں سے ملاقاتیں اور کچھ مشاہدات(ان کا ذکر دلی کے احوال میں آگے چل کر ہو گا)۔
۱۷؍ اپریل کی شام۵ بج کر ۵۰ منٹ پرایر انڈیا کی پرواز IC 540سے روانہ ہو کر۸ بجے شب حیدرآبادپہنچا۔ اتفاق سے عین اسی وقت سری نگر سے آنے والی پرواز سے ڈاکٹرشکیل الرحمن بھی حیدرآباد ہوائی اڈے پہنچے تھے۔ انتظار گاہ میںباہمی تعارف ہوا۔ میں نے گذشتہ شب اقبال اکیڈمی کے نائب ناظم محمد ظہیرالدین صاحب کوتار دیاتھا کہ ایئر انڈیا کی پرواز سے حیدر آباد پہنچ رہا ہوں۔ یہاں پہنچ کراندازہ ہواکہ تارانھیں نہیں ملا۔تیس برس پہلے تک پاکستان اور بھارت میں اچھی یا بری فوری اطلاع دینے کا ارزاں طریقہ’’ تار‘‘تھاجو ڈاک خانے ہی سے بھیجی جاتی تھی۔ٹٰیلی فون بہت گراں تھا اور مشکل ہی سے ملتا تھا۔اس زمانے میں ڈاک خانے کا نام تھا: پاکستان پوسٹ اینڈٹیلی گراف ۔
رحیم قریشی صاحب(نائب صدر سیمی نار ) اور خواجہ ناصر الدین صاحب(جوائنٹ سیکرٹری) شکیل الرحمان صاحب کو لینے آئے تھے، اچانک مجھے پاکربہت خوش ہوئے۔ ڈیڑھ گھنٹے میں،مجھے بھی انھوں نے پریذیڈنٹ ہوٹل پہنچا دیا۔اگروہ نہ ملتے تو سخت پریشانی ہوتی کیوں کہ ہوائی اڈّا شہر سے تقریباًپچاس میل کی دوری پرواقع تھا۔مسافر رات کے ٹھکانے سے بے خبر، کہاں جاتا۔
پرپریذنٹ ہوٹل معظم جاہی روڈ پر قلبِ شہر میں واقع تھا۔ کمرا نمبر ۵میں مقیم ۔دیرہوچکی تھی، ہوٹل کاکچن بند ہو چکا تھامگر چائے میسر آ گئی۔کچھ اور کی ضرورت بھی نہ تھی اور بھوک نہ تھی کیوںکہ جہاز میں کچھ کھالیاتھا۔
۱۸؍ اپریل: نمازِ فجر کے بعد افضل گنج تک سیر کے لیے گیا۔ موسی ندی کے کنارے جھگیاںانتہائی غلیظ،مکین مفلوک الحال ۔ فٹ پاتھوں پربہت لوگ سو رہے تھے۔ عثمانیہ ہسپتال کے سامنے کا لان کسی زمانے میں خوب صورت پارک رہا ہو گا۔اب تو ایک گوشے میں چند قبریں ہیں خستہ حالت میں اور اِرد گرد غلاظت۔۔۔ فاتحہ پڑھی اور واپس۔
ناشتہ کمرے ہی میں مل گیا۔ سیمی نار سہ پہر میں شروع ہونے والا تھا۔ معلوم ہوا پروفیسر اسلوب احمدانصاری، پروفیسر عبدالحق اورمعین الدین عقیل بھی پہنچ گئے ہیں۔ اسلوب صاحب سے خط کتابت تو تھی ،اب ملاقات باعثِ مسرت ۔ ان کی تحریروں سے اُن کی شخصیت اور مزاج کا کچھ اندازہ ہوتاتھا۔ ملاقات سے قربت کااحساس بڑھ گیا۔ سیمی نار کا مفصل پروگرام موصول ہو گیا۔
معروف محقق ،نقاد اور مترجم جناب حسن الدین احمد صاحب سے ملاقات مقصود تھی۔عقیل صاحب نے فون کیا۔ انھوں نے گاڑی بھیج دی۔ ان کے مکان ’’عزیز باغ‘‘ میں تقریباً ایک گھنٹا ملاقات رہی۔ حسن الدین احمد کا تعلق حیدر آباد کے ایک معزز گھرانے سے ہے۔ان کے دادا نواب عزیز یار جنگ وِلا ریاست میں اونچے مناصب پر فائز رہے۔ محقق اور جامع الکمالات شخصیت تھے۔ بیسیوں کتابوں کے مصنف ۔دو جلدوں میں تاریخ النوائط لکھی۔ لغتِ آصفیہ ۱۴ جلدوں میں مرتب کی، صرف ’ج‘ تک ہو سکی۔ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے۔ حسن الدین احمد کی وضع دار شخصیت نے بہت متاثر کیا۔میں نے انھیں اپنی دو کتابیں پیش کیں۔انھوں نے بھی اپنی چار تصانیف تصانیف عنایت کیں ۔دادا کی طرح وہ بھی ایک محقق اور سکالر ہیں۔ ’’انگریزی نظموں کے منظوم اردو تراجم ‘‘ پر انھوں نے پی ایچ ڈی کیاتھا۔ اپنے مقالے کے علاوہ انھوں نے منظوم تراجم کو مرتب کر کے دس جلدوں میں شائع کر دیاہے۔ عزیز وِلا سے نکل کر ہم حسّا می بک ڈپو پر گئے ،چند کتابیں خریدیں۔ وہاں سے مکہ مسجد میں نمازِ جمعہ ۔ قطب شاہی عہد کی یہ تاریخی مسجد پتھر کی ہے۔مسجد میں صفائی عنقا۔وضو کے لیے تالاب ہیں، استنجا خانے گندے۔ شامیانے کم ،نمازی زیادہ۔گرمی تھی مگر کئی لوگ شیروانی میں ملبوس، حتیٰ کہ ایک بھکاری بھی شیروانی پہنے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔گداگر بہ کثرت۔
نظام عثمان علی کے پوتے شہزادہ مفخر جاہ نمازِ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ساتھ ترکی ٹوپیوں والے ذاتی محافظ مگر یہ سرکاری پولیس کے ماتحت تھے۔مسجد سے نکل کر بالکل قریب ہی چار مینار دیکھا۔چار سو سالہ پرانی یادگار، پُر شکوہ اور عالی شان۔اس کے ایک کونے میں ہندوؤں نے ایک مندر بنا لیا ہے۔
عقیل صاحب نے عقب میں ایک کہنہ کتاب فروش کی دکان تلاش کی۔دام زیادہ تھے تاہم چند کتابوں کی فرمائشیں لکھوا کر واپس ہوٹل۔کچھ دیرآرام کیا،بعدہ، سب مندوبین جلسہ گاہ پہنچے۔نمائش کا افتتاح ہو چکا تھا۔ جگن ناتھ آزاد اور دیگر مندوبین سے ملاقات ہوئی۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت سیدمظفر حسین برنی نے کی۔ اُن دنوں وہ صوبہ بہار کے گورنر تھے۔ اسٹیج پروزیراعلیٰ بھی براجمان تھے۔
اس اجلا س کی مفصل کارروائی’’اقبال پر ایک یادگاراجتماع‘‘ کے عنوان سے مجلہ اقبالیات لاہور ( جولائی تا ستمبر ۱۹۸۶ء) میں لکھ چکا ہوں۔ افتتاحی اجلاس کی ایک دو باتیں قابل ذکر ہیں :ایک یہ کہ آغاز’’ترانۂ ہندی‘‘(سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا) سے ہوا،جسے مقامی فائن اکیڈمی کے فن کاروں نے سازوں کی مدد سے گایا۔’’ہندی ہیں ہم ‘‘کے ٹکڑے کو بطورِ خاص تین مرتبہ گایا گیا۔آندھرا پردیش کے وزیرِ اعلی این ٹی راما رائو کی سہ لسانی(انگریزی ،تیلگو ، اردو)تقریر بہت دل چسپ تھی۔تقریر کے بعد انھو ں نے اپنے مخصوص لہجے میں’’ ترانۂ ہندی‘‘ ’’ہندوستانی بچوں کا قومی گیت ‘‘اور’’ نیا شوالہ‘‘ کے بعض اشعار لہک لہک کر پڑھے تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا ۔ان کے ہندی زدہ لہجے نے محفل کو شگفتہ بنا دیا۔انھوں نے بعض مصرعے اس انداز سے پڑھے کہ سامعین کو لطف دے گئے،مثلاً:
جس نے ’’حجاجیوں‘‘ کو دشتِ عرب سے چھڑایا
___________ __
مٹی کو جس نے ’’جر ‘‘کا اثر دیا تھا
____________
خاکِ وطن کا مجھ کو ہر’’ جرہ‘‘دیوتا ہے
____________
برنی صاحب کی صدارتی تقریر طویل اور اُکتا دینے والی تھی۔خاص طور پر اسلوب صاحب بہت منغّض تھے۔کہنے لگے: جب مجھے پتا چلا کہ سیمی نار میں برنی صاحب بھی آ رہے ہیں تو میں نے شمولیت کا ارادہ منسوخ کر دیا مگر دہلی سے حیدر آباد کی بُکنگ کرا چکا تھا ، چلا آیا۔
۲۰؍اپریل (اتوار) کوسہ پہر کے اجلاس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔علی سردار جعفری تقریر کر رہے تھے کہ عقب سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر نہایت پھرتی سے سردار جعفری کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیا۔پھر اسی تیزی سے مڑ کر بھاگ گیا۔کچھ لوگ اس کے پیچھے لپکے مگر وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔منتظمین کی کوشش سے اس شرم ناک حرکت کی خبر،ایک آدھ کے سوا کسی اخبار نے نہ شائع کی۔ اجلاس کے دیگر مقررین اور منتظمین نے اس کی مذمت کی۔
نوجوان کی اس حرکت کا پس منظر یہ ہے کہ ان دنوں بھارتی حکومت نے کچھ ایسے عائلی قوانین منظور کیے تھے جو شریعت اسلامیہ سے متصادم تھے۔مسلمان اس کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج کر رہے تھے مگر ترقی پسند گروہ حکومت کا مؤید تھا ۔سردار جعفری ترقی پسندوں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔
۱۹ اپریل کو پہلے سیشن کی صدارت گوپال ریڈی نے کی تھی، انھوں نے تیلگو میں اقبال کے منتخب کلام کا ترجمہ کیا ہے۔ صدارتی تقریر میں انھوں نے ’’اقبال بحیثیت شاعر‘‘ پر زور دیا۔ اس سیشن میں بھی ’’ سارے جہاں سے اچھا ۔۔۔ ‘‘ کی لَے نمایاں رہی۔
سیمی نار کے سامعین میں دکن کے دُور دراز علاقوں سے والوں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبانِ اقبال شامل تھے۔سکول کالجوں کے اساتذہ، ریلوے کے ملازم، ڈاک خانے کے انسپکٹر،انجنیئر اور دیگر ملازمین۔معلوم ہوا،پربھنی(حیدر آباد سے ۲۱۰ میل دُور) میں بھی کُچھ عقیدت مندوں نے اقبال اکادمی قائم کر رکھی ہے۔
سیمی نار کے مندوبین میں پروفیسر آل احمد سرور، پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر نثار احمد فاروقی سے تو ملاقات تھی۔باقی اصحاب کی زیارت پہلی بار ہوئی۔ شمس الرحمٰن فاروقی،عبدالستار دلوی، ممنون حسن خاں، آفاق احمد،علی سردار جعفری،جگن ناتھ آزاد، گوپی چند نارنگ،شکیل الرحمٰن ، عمر کٹّی وغیرہ۔
سیمی نار ختم ہواتودہلی واپسی میں تین روز باقی تھے۔ ظہیر الدین صاحب نے ہمیں حیدرآباد کے قابل دید مقامات دکھانے کا پروگرام بنارکھاتھا۔ چنانچہ صبح ناشتے کے بعد انھوں نے ہمیں وجیہ الدین احمد کی راہ نمائی میں حیدر آباد کی سیاحت پر روانہ کر دیا۔وہ خود بہت دنوں سے چھٹی پر تھے۔آج دفتر میں حاضری ضروری تھی۔ وجیہ الدین احمد ہمیں ایک موٹر میںلے چلے۔وجیہ صاحب مقامی اوپن یونی ورسٹی میں اردو کے لیکچرار تھے۔میری طرح تھے تو دھان پان مگر مہمانوں کی خاطر تواضع اور رہنمائی میں انھوں نے کمال مستعدی دکھائی۔دن بھر مختلف یادگاریں دیکھنے میں گزرا۔ اِن میں چار مینار، سالار جنگ میوزیم، جامعہ عثمانیہ،قطب شاہی مقبرے، قلعہ گول کنڈااور بعض ڈیم شامل تھے جن میں بارش کا پانی ذخیرہ کرکے حیدرآباد شہر کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔
یوں توسبھی یادگاریں قابل دیدتھیں لیکن سالارجنگ میوزیم نوادرات وعجائبات سے معمور تھا،جہاں ہم ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی گزارسکے مگر جی چاہتاتھاکہ کم ازکم ایک دن یہاں بسرکیجیے۔ ایک جگہ ایک بہت بڑا کلاک بنا ہواتھا۔ بنانے والے نے ایسی تکنیک سے بنایاتھاکہ ہرگھنٹے کے موقع پرکلاک کے عقب سے ایک آدمی نمودار ہوتاتھااوروقت کی مناسبت سے دوبجے ہوں تودودفعہ،تین بجے ہوں توتین دفعہ، علیٰ ہٰذالقیاس، بارہ بجے تک گھنٹا بجاتاتھا،جس طرح اسکولوں میں ٹن ٹن کی گھنٹی بجاتے ہیں۔سالارجنگ میوزیم کیاچیز ہے ؟اس کے مفصل تعارف کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مختصر یہ کہ میوزیم کی وہ عمارت ۳۵کمروں پر مشتمل تھی جس میں ۳۵ہزار اشیانمائش کے لیے رکھی ہوئیں تھیں۔ مختلف ممالک کے لباس،جوتے،فرنیچر،برتن،گھڑیاں،قالین،تصویریں،پلنگ،کمبل،پنکھے،آلاتِ زراعت،جنگی اسلحہ اور ہتھیار،الماریاں،چولھے،کھیلوں کا سامان اور مصوّری کے نمونے(ان میں عبدالرحمن چغتائی کے فن پارے بھی ہیں ) وغیرہ ۔ ایک ایک چیز کے دس دس پندرہ پندرہ نمونے اوراقسام۔(میوزیم اب غالبا کسی اور عمارت میں منتقل ہو گیا ہے۔) نواب سر سالار جنگ نے جو ریاست حیدرآبادکے وزیراعظم بھی تھے،اپنے ذوق کی تسکین کے لیے دنیا بھر میں گھوم پھر کریہ نوادرات جمع کیے تھے۔
ان کا اصل نام میر یوسف علی خاں تھا۔ والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس لیے جاگیر Court of Wardکی حیثیت سے حکومت کی نگرانی میں چلی گئی اورایک انگریز مسٹر ڈنلاپ اس کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ۔پھر بالغ ہونے پر وہ اپنی جاگیر کے مالک بنے۔ کچھ عرصہ چیف منسٹری کی آبائی خدمت بھی انجام دی۔سالار جنگ کو بچپن ہی سے نوادرات خریدنے کا شوق تھا۔ سیروسیاحت کے دل دادہ تھے۔انھوں نے دنیا کے مختلف ممالک کی سیاحت کے دوران مختلف علاقوں سے طرح طرح کے نوادرات خریدے اورکتابیں فراہم کر کر کے میوزیم میں جمع کرتے رہے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ تین منزلہ عمارت بنائیں ، ہر منزل کے۱۰۰ کمرے ہوں ، مجوزہ عمارت کا نقشہ بنا،زمین منتخب ہوئی مگر عملاًابھی کچھ نہ کر پائے تھے کہ اللہ میاں نے بلا لیا۔
جب سالار جنگ فوت ہوئے تو حکومت اورورثا کے درمیان کئی سال کشمکش رہی،ایک عارضی کمیٹی نے انتظام سنبھالا جس کے تحت سالارجنگ کے مکان کے بڑے حصے میں میوزیم تو قائم رہا مگرصدرکمیٹی نے کتب خانے کو نظر انداز کر دیا ۔ خدا بھلا کرے، انجمن ترقی اردو اور نواب علی یارجنگ کا جن کی توجہ سے کتب خانہ ضائع ہونے سے بچ گیا۔ میوزیم مع کتب خانہ نشیب و فراز سے گزرتا رہا۔ کئی سال بعد یہ مرکزی حکومت کی تحویل میںچلا گیا جس نے میوزیم کے لیے ایک عالی شان عمارت کی منظوری دی۔یہ بہت ہی نایاب ذخیرہ ہے، دس ہزار تو قلمی کتابیں ہیں اور دو ہزار ایسے مخطوطے ہیں جن کا کوئی اور نسخہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ (نصیرالدین ہاشمی،ہماری زبان،یکم فروری۱۹۵۹ء)
شہر میں گھومتے ہوئے کچھ دور تک ہم موسی ندی کے کنارے بھی چلے۔ ندی کے کنارے بعض نہایت شاندار عمارات واقع ہیں ،جیسے سرکاری ہسپتال یا کتب خانہ ء آصفیہ (سٹیٹ سنٹرل لائبریری )وغیرہ۔ نظام کے محلات دورسے دیکھے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے مولاناظفر علی خان یاد آئے جنھوں نے موسی ندی کی۱۹۰۸ء کی طغیانی کے بعد حکومت کے قائم کردہ افضل گنج کے لنگرخانے کا نہایت عمدہ انتظام کیاتھا۔موسی ندی کا یہ سیلاب بہت ہول ناک تھا جس نے بڑی تباہی مچائی تھی۔روایت ہے کہ تقریباً ۱۰ تا ۱۵ ہزار لوگ اس طغیانی کی نذر ہو گئے۔ ۱۹ ہزار مکانات منہدم ہوئے۔ تقریباً ۸۰ ہزار افراد بے گھر ہو گئے اور تین کروڑ روپے (اس زمانے کے تین کروڑ )کا مال و اسباب برباد ہو گیا۔ عمارتوں کی چھتوں، اونچے پلوں اور درختوں پر پناہ لیے ہوئے لوگ بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ جونہی سیلاب ختم ہوا حکومت نے کئی جگہ لنگرخانے کھول دیے۔ مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں حیدر اآباد میں مقیم تھے۔ انھیں محلہ افضل گنج کے لنگر خانے کا مہتمم مقرر کیا گیا۔ کچھ سرکاری ملازمین ان کی اعانت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ لنگر خانہ ۱۵ دن قائم رہا۔ ۵ ہزار آدمیوں کو دو وقت کھانا دیا جاتا تھا۔ ظفر علی خان شاعر، مقرر اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت عمدہ منتظم بھی ثابت ہوئے ۔ انھوں نے کمال لیاقت و قابلیت اور حسنِ تدبیر و تنظیم سے لنگر خانے کو چلایا۔ حکومت کے ہندو مسلم اور انگریز عہدے داروں نے ان کی تعریف کی۔ ظفر علی خاں نے تیس صفحات پر مشتمل رپورٹ مرتب کر کے رپورٹ کار گزاری لنگر خانہ افضل گنج کے نام سے شائع کر دی۔ راقم نے اپنی کتاب تفہیم و تجزیہ (لاہور ۱۹۹۹ء) میں اس رپورٹ کے حوالے سے ظفرعلی خان کے کارنامے کا تعارف کرایاہے۔ عنوان ہے: ’’حیاتِ ظفر علی خان کا ایک ورق‘‘۔
مجھے بانگِ درا کی نظم ’’ گورستانِ شاہی‘‘ کے حوالے سے قطب شاہی بادشاہوں کے مقابر دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ یہ مقابر شہر سے دس کلومیٹر باہر واقع ہیں۔ علامہ اقبال نے رات کی چاندنی میں مقبروں کا نظارہ کیا تھا۔ حیدر آباد میں ان کے میزبان سر اکبر حیدری تھے۔اقبال لکھتے ہیں کہ اکبر حیدری:’ ’مجھے ایک شب ان شاندار، مگر حسرت ناک گنبدوں کی زیارت کے لیے لے گئے، جن میں سلاطینِ قطب شاہیہ سو رہے ہیں۔ رات کی خاموشی، ابر آلود آسمان اور بادلوں میں سے چھن کر آتی ہوئی چاندنی نے اس پُرحسرت منظر کے ساتھ مل کر، میرے دل پر ایسا اثر کیا، جو کبھی فراموش نہ ہوگا‘‘۔ بانگِ درا کی نظم’’گورستانِ شاہی‘‘علامہ کے اسی سفر کی یاد گار ہے۔
ہم دوپہر کے وقت وہاں پہنچے تھے ۔فضا میں تمازت تھی ۔گھوم پھر کر مقبرے دیکھے ۔سب مقبروں کا انداز ایک جیسا تھا ۔ادھر ادھر عام لوگوں کی قبریں بھی تھیں ۔درمیان میں اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ ایک مسجد بھی ہے ۔میں درخت کی سائے میں ایک قبر کے کنارے بیٹھ گیا۔’’بانگِ درا‘‘ کھولی،نظم ’’گورستانِ شاہی‘‘دیکھنے لگا۔
سوتے ہیں خاموش ، آبادی کے ہنگاموں سے دُور
مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوے ناصبور
قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک
جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبیںگستر فلک
کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مآل
جن کی تدبیرِ جہاںبانی سے ڈرتا تھا زوال
رعبِ فغفوری ہو دنیا میں کہ شانِ قیصری
ٹل نہیں سکتی غنیمِ موت کی یورش کبھی
بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حاصل ہے گور
جادئہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور
ماحول میں خاموشی تھی۔ مقبرے اونچی جگہ واقع تھے اور دونوں اطراف نشیب میں جنگل نظر آ رہا تھا۔قبروں کی زیارت یوں بھی عبرت دلاتی ہے اور علامہ بھی کَہ رہے تھے:
بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حاصل ہے گور
جادئہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور
یہاں دنیا کی بے ثباتی ،اور حکمرانی وجاہ و منصب کی بے حیثیتی کا احساس ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ وہ عظمت کی جتنی بلندیوںتک بھی چلا جائے، آخر کار اسے مٹی ہی میں مل جانا ہے ۔
دکن کے قابلِ دید مقامات میںسے ایک اور قابلِ دید چیز قلعۂ گول کنڈا ہے جو ایک زمانے تک قطب شاہی حکومتوں کا صدر مقام رہا ۔ یہ شہر سے گیارہ کلومیٹر باہر واقع ہے۔ چار پانچ صدیاں پرانا قلعہ، پانچ میل کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ۹ دروازے اور ۵۲ کھڑکیاں ہیں۔ فصیل پر ۴۸ برج ہیں۔ ۱۸۶۷ء میں اورنگ زیب عالم گیر ۸ ماہ یہاں مقیم رہا۔ موسم گرم تھا اور وقت پختہ دوپہر، مسلسل چڑھائی، اوپر کے محلات تک پہنچتے پہنچتے میں تو نڈھال ہو گیا مگر یہاں سے چاروں طرف کا نظارہ خوب تھا۔ کھیت، جنگل اور کہیں کہیں آبادی۔ ایک دوسرے کو قطع کرتی سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک، کاریں اور موٹریںبلندی سے ماچس کی ڈبیائیں معلوم ہوتی تھیں۔قلعے کی بناوٹ میں خاص بات یہ ہے کہ معماروں نے نیچے کے داخلہ دروازے سے لے کر چوٹی کے محلات تک راستوں، دیواروں اورگنبدوں کی بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ اگر نیچے کھڑے ہوئے تالی بجائیں تو اس کی آواز چوٹی تک پہنچتی ہے جواکسٹھ میٹر بلند ہے،اور اگر چوٹی پر کسی خاص جگہ تالی بجائیں تو آواز نیچے سنائی دیتی ہے ۔ایک کتابچے میں بتایا گیا ہے۔
The most remarkable feature of this fort is the system of acoustic,where-by a clapping of the hands at the entry gate can be heard at the top of the Fort some 6 meter high.
کہا جاتا ہے کہ تالی کی مختلف طرح کی آوازوں کے کوڈ مقرر کیے گئے تھے جن کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی۔
قدیم عمارتوں اور قلعوں، خاص طور پر مغلوں کی تعمیرات میںاس طرح کی ڈیوائس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔
بالکل زمانۂ حال کی ایک مثال تو سامنے کی ہے۔ خانوادۂ سر سید احمدخاں کے ایک بزرگ، آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ اور عربی زبان و ادب کے فاضل، ڈاکٹر سیدعابد احمد علی، تقریباً آٹھ برس تک گورنمنٹ کالج سرگودھا کے پرنسپل رہے۔ کالج کے وسیع کیمپس میں مسجد نہ تھی۔ یہ چیز انھیں کھلتی تھی ۔پروفیسر صاحب زادہ عبد الرسول صاحب کے بقول :ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مملکتِ خدادا د پاکستان میں کسی تعلیمی ادارے کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس میں ایک نہایت شاندار مسجد موجود نہ ہو ۔انگریزوں نے برصغیر میں جہاں بھی تعلیمی ادارے قائم کیے، ان کے ساتھ خوبصورت گرجے بھی قائم کیے۔ڈاکٹر صاحب کے خیال میں کسی تعلیمی ادارے میں گرجے یا مسجد کی محض موجودگی طلبہ کے لا شعور اورانداز فکر پراثر انداز ہوتی ہے۔چنانچہ ڈ اکٹر صاحب نے سرکار سے اجازت لے کرطلبہ پر ایک روپیا ماہوار مسجد فنڈ عائد کر دیا جو فیسوں کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ کچھ مخیر حضرات نے عطیات بھی ؓؓؓؓؓؓؓؓؓدیے۔خیال رہے کہ اس زمانے میں کسی گورنمنٹ کالج میں مسجد کا تصور ،خیالِ خام تھا لیکن ڈاکٹر صاحب عزمِ صمیم رکھتے تھے۔ حکومت سے اجازت حاصل کرکے مسجد تعمیر کی۔ مسجدکی محراب، مسجدِ قرطبہ کی محراب طرز کی تھی۔ اس محراب کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس میں کھڑے ہو کرجو کلمات کہے جائیںوہ، مسجد کے مسقف حصے اور صحن میں ہر جگہ، بلکہ مسجد سے باہر بھی سنے جا سکتے تھے ۔ اگر مسجد کے احاطے میں داخلے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بات کی جاتی یا کوئی کلمہ ادا کیا جاتا تو محراب میں آواز صاف سنائی دیتی تھی حالانکہ اتنے فاصلے پر آواز کسی تار کے بغیر نہیں پہنچتی۔افسوس ہے کہ چند برس قبل مسجد کامحراب توڑ کر مغربی رخ پر مسجد میں توسیع کی گئی اور اس کے نتیجے میں محراب کی یہ نادر خوبی ختم ہو گئی۔ اسے اب ’’جامع عابد‘‘ کا نام دیا گیا ہے۔
اگر گول کنڈا سے قطب شاہی مقابر کی طرف جانا چاہیں تو بائیں گھوم کر جاتے ہیں ۔گول کنڈا سے مغرب کی طرف جانے والی سٹرک گنڈی پیٹ تالاب پر بنے پل سے گزرتی ہے۔دراصل یہ بہت لمبی جھیل ہے۔
ان دو دنوں میں تاریخی آثار دیکھنے کے علاوہ ، بعض اداروں (جامعہ عثمانیہ، کتب خانہ آصفیہ، ادارہ ادبیات اردو اور آندھرا پردیش سٹیٹ آرکائیوز ) جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ جامعہ عثمانیہ کی موجودہ عمارت ۱۹۴۰ء میں مکمل ہوئی تھی۔ دو منزلہ عمارت میں نیچے کی منزل ہندو فنِ تعمیر اور اوپر کی عمارت مسلم فنِ تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کی کھڑکیاں مسجد قرطبہ کی محرابوں کی طرز پر ہیں۔ دیواریں، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ساڑھے تین فٹ دبیز ہیں۔شعبہ اردو میں ڈاکٹر یوسف سرمست ، ڈاکٹر مرزا علی اکبر بیگ، ڈاکٹر سیدہ جعفر ،اشرف رفیع، اور بیگ احساس اور شعبہ اسلامیات میں ڈاکٹر انور معظم سے ملاقات ہوئی ۔ یہ سب حضرات سیمی نار میں بھی آتے رہے۔کیمپس بہت وسیع ہے۔ کالج آف ایجوکیشن ،آرٹس کالج، لا کالج، انجینئر نگ کالج، سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انگلش اینڈ فارن لینگوئجز کے درمیان ٹیگور آڈی ٹوریم واقع ہے۔ یونی ورسٹی کتب خانے کا حوالہ جاتی سیکشن خاصا بڑا ہے۔ مگر پاکستانی کتابیں بہت کم ہیں۔ ایک لائبریرین نے کہا ہم پاکستانی کتابوں کے لیے ترستے ہیں۔ وائس چانسلر کے دفتر پر بھارتی جھنڈا لہرا رہا تھا۔
خیرت آباد کے پنج گٹہ روڈ پر ادارہ ادبیات اردو کی عمارت تو خوب صورت ہے مگر انتظام اچھا نہیں ہے۔ میوزیم نادر مخطوطات ،فرامین، سکوں، ہتھیاروں اور کتبوں پر مشتمل ہے۔ دیکھ بھال کا انتظام معقول نہیں ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے جانے کتنے جتنوں سے یہ نوادر جمع کیے ہوں گے ۔ عقیل صاحب نے بتایا ہے کہ اب یہ ادارہ ایک نئی عمارت میں منتقل ہو چکا ہے اور اس کی حالت بہت بہتر ہے۔
آندھر ا پر دیش سٹیٹ آرکائیوز کا چکر بھی لگایا، وہاں سے حوالے کی چند کتابیں خریدیں۔ دائود اشرف اور شکیل احمد صاحبان سے ملاقات ہوئی، دونوں حضرات نے آرکائیو سے نادر چیزیں نکال کر شائع کی ہیں۔ شکیل صاحب کی اقبال پر نئی تحقیق تو اقبالیات پر اہم اضافہ ہے۔
کتب خانۂ آصفیہ ، حیدر آباد کا بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ کچھ وقت وہاں گزرا۔ اندازہ ہوا کہ پاکستان کی نسبت وہاں کے طلبہ و طالبات میں لائبریری میں بیٹھ کر کام کرنے کے رجحان زیادہ ہے۔ کتب خانہ آصفیہ کے بعض حصے رات ۱۲ بجے تک کھلے رہتے ہیں۔
حیدر آباد کے بعض ادبی اکابرکا ذکر کتابوں ،رسالوںمیں پڑھا تھا ،کبھی زیارت نہ ہوئی تھی۔ گذشتہ ۵،۶ روز میں وقت نکال کر ہم نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ اقبال اکادمی کے بانی خلیل اللہ حسینی گو ایک روز سیمی نار میں کُچھ دیر کے لیے آئے تھے ،مگر کچھ دیر بیٹھ ،خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے،ان سے ملناضروری تھا،اس لیے ایک روز ہم نے اُن کے ہاں حاضری دی۔نوجوانوں کو مطالعۂ اقبال کی طرف راغب کرنے،پھر اقبال اکادمی کا قیام اُن کا بڑا کارنامہ ہے۔سیمی نار کی ایک نشست کے دوران ،اجازت لے کر ،ہم نے دکن کے معروف اقبال شناس جناب غلام دستگیر رشید کے ہاں بھی لال ٹیکری میں اُن کے مکان پر حاضری دی۔اُن کی عمر اسی (۸۰) سال ہے۔ دکن میں فروغ اقبالیات میں ان کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔ وہ حیدر آباد میں ایک زمانے تک ہفتہ وار درسِ اقبال دیتے رہے۔فرمایا: میں کلامِ اقبال کی ترتیب کے مطابق درس دیا کرتا تھا۔انھوں نے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا بھی ذکر کیا۔دکن میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر بات ہونے لگی۔کہنے لگے: قاسم رضوی کی جذباتیت اور جلد بازی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں، کوئی قوم زوال پذیر ہو تو ایسا ہوتا ہے۔مولانا مودودی کا ذکر آیا، کہا:وہ اسمبلیوں کے مخالف تھے اور ملازمتوں میں جانے کو غلط سمجھتے تھے ،اس لیے میں اور مولانا مناظر احسن ، اُن سے الگ ہو گئے۔
اسی طرح معروف محقق حسینی شاہد اور ان کی بیگم زینت ساجدہ سے بھی ان کے گھر میں مختصر ملاقات کی۔وہ ماں صاحب پیٹ کے علاقے میں رہتے تھے۔ عقیل صاحب تو حیدر آباد کے بہت سے لوگوں سے ربط وضبط رکھتے تھے۔ بعض حضرات میرے نام سے بھی واقف تھے چناچہ بہت سے کرم فرمائوں نے دعوت طعام یاچائے کے لیے گھر بلانا چاہا، ہم نے طے کر لیاتھا کہ کسی دعوت میں نہیں جائیں گے۔ مگر ہمارا یہ عزم برقرار نہ رہ سکا ۔بزرگ محقق اکبر الدّین صدیقی ایک روز ہوٹل تشریف لے آئے اور ایک شام دعوت کے لیے اصرار کیا۔ وہ اس پیرانہ سالی میں رکشا پر آئے تھے، ہم انکار نہ کر سکے اور دوسرے دن ان کے ہاں حاضری دینی پڑی ۔
ایک سہ پہر اُردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے سیمی نار کے مندوبین کے اعزاز میں عصرانہ دیا۔مختصر سا مشاعرہ بھی ہوا۔اسی شب سیمی نار کے نائب صدر شاہ عالم صاحب نے نظام کلب میں مندوبین کو عشائیہ دیا۔یہاں بہت سے حیدرآباد ی رئوسا سے ملاقات ہوئی ۔بعدہ‘ ’’شبِ اقبال‘‘ میں رات گئے دیر تک کلامِ اقبال گایا جاتا رہا۔ طبیعت مضمحل تھی،نہ جا سکا۔صبح عقیل صاحب نے بتایاکہ کلام اقبال گانے والوں نے سماں باندھ دیا۔
بعض دوست ہوٹل میں آتے رہے۔ڈاکٹر محمد علی اثر علیل تھے مگر زحمت کر کے ملنے آئے۔چند تصانیف عنایت کیں ان میں کتابیاتِ دکن ود کنیات بھی تھی جسے راقم کی درخواست پر استاد محترم ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد سے شائع کردیا۔بعض ازاں اثر صاحب سے خط کتابت جاری رہی۔جامعات کے تحقیقی مقالات سے متعلق انھوں نے قیمتی معلومات مہیا کیں۔اسی طرح ڈاکٹر مرزا اکبر علی بیگ اور ڈاکٹر یوسف اعظمی بھی تشریف لائے۔دعوت طعام سے تو معذرت کی مگر تصانیف بصد مسرت قبول کیں ۔افسوس ہے کہ میرے پاس ان حضرات کو تحفہ دینے کے لیے اپنی کتابیں نہیں تھیں۔لاہور پہنچ کر ،مقدور بھر تحائف دوستوں کو روانہ کیے۔
میرے دوست محمد رفیع الدین فاروقی ( متعلّم ایم فل ) ایک روز نواب مرزا داغ(’’شاعرِ ضریح‘‘) اور امیر مینائی کی قبریں دکھانے لے گئے ۔ اس طرح فاروقی نے وہ کمرا بھی دکھایا جس میں ابو محمد مصلح کے جاری کردہ رسالے ترجمان القرآن کا دفتر قائم تھا۔ بعد ازاں یہ رسالہ ان سے مولانا مودودی نے لے لیا۔ قیاس ہے کہ اس دفتر میں مولانا کی آمد ورفت رہی ہو گی۔اس کمرے پر ’’عالمگیر تحریکِ قرآن‘‘ کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ابو محمدمصلح کی صاحب زادی سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ترجمان القرآن کی جلد اوّل اور قرآن اور اقبال طبعِ اوّل کا نسخہ عنایت کیا۔قیمت دینا چاہی، کہا: یہ تحفہ ہے۔
اگلے روز عقیل صاحب علی الصبح کسی دوست کے ساتھ بیدر، اودگیر اور اورنگ آبادکے سفر پر روانہ ہوئے۔ اودگیر اُن کی جائے ولادت ہے،جس کی زیارت کے لیے ان کا اشتیاق قدرتی تھا۔جی تومیرا بھی بہت چاہتا تھا کہ اورنگ آباد(اورنگزیب عالمگیر کا مدفن اور سید ابوالاعلیٰ مودودی کا شہرِ ولادت) دیکھوں مگر یہاں حیدر آباد میں مجھے چند زیادہ ضروری کام تھے اس لیے باز رہنا پڑا۔
ڈاکٹرگیان چند سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔وہ اس زمانے میں حیدرآباد کی سنٹرل یونی ورسٹی سے وابستہ تھے۔ سیمی نار میں بطور مقالہ نگار مدعوتھے مگر سوئے اتفاق سے وہ صرف ایک روز ہی سیمی نار میں آسکے کیوں کہ چندروز پہلے ان کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی اوروہ چلنے پھرنے میں دِقت محسوس کرتے تھے۔ یوں ملاقات،جوہم دونوں کی خواہش تھی کہ طویل ہونی چاہیے،بہت مختصررہی۔ ان کی قیام گاہ دورتھی اورسیمی نارکے بعدحیدرآباد میںمیرا قیام صرف تین روزتھا۔
پہلے دو روزحیدرآبادکے قدیم تاریخی آثار ومقامات دیکھنے اورصوبائی محکمہ آثار قدیمہ کے دفاتر میں بعض اقبال دوستوں سے ملاقاتوں میں صرف ہوگئے۔
سیمی نارکی مختصرملاقات میں،گیان چندمجھے سنٹرل یونی ورسٹی کیمپس میں واقع اپنے مکان پرمدعوکرگئے تھے اور میں نے حاضر ہونے کاوعدہ بھی کرلیاتھا مگر وقت کم تھااورکام زیادہ۔میرے پا س صرف ایک دن آخری بچاہواتھا۔کام دوتھے:
۱۔ڈاکٹرگیان چند سے ملاقات
۲۔اقبال اکیڈیمی کے کتب خانے سے کتابیاتِ اقبال کے لیے معلومات ،حوالوں اورلوازمے کاحصول۔
یہ دونوں کام بہت اہم تھے۔ ایک شب پہلے تو میں شش وپنج میں رہا،پھر میں نے کتب خانے سے استفادے کواولیت دینے کا فیصلہ کیاا وریہ فیصلہ درست ثابت ہوا کیوں کہ اکیڈیمی کا کتب خانہ دوبارہ دیکھنے کاآج تک موقع نہیں ملا جبکہ گیان چند صاحب سے ملاقات کا موقع چندسال بعد لاہورمیں نکل آیا۔
اقبال اکیڈیمی کے کتب خانے پہنچا۔ ذخیرئہ اقبالیات دیکھ کر اندازہ ہواکہ کتب خانے میں بیٹھ کر کام مکمل کرلینا ممکن نہ ہوگاکیوں کہ لوگوں کی آمدورفت اورملاقاتوں میں کام نہیںہوسکتاتھا،جن جن کتابوں سے معلومات اخذ کرنا مقصودتھا،وہ سب ظہیرالدین صاحب نے الگ نکلواکرمیرے ہوٹل کمرے میں پہنچا دیں۔ میں پورا دن کتابوں،رسالوںاورکتابچوں کے کوائف نوٹ کرتارہا،حتیٰ کہ شام پڑگئی۔ سو چا تھا کہ اگر شام کو وقت نکلا تو گیان چند سے ملنے چلا جاؤں گا۔معلوم ہواکہ سنٹرل یونی ورسٹی کیمپس خاصا دورہے۔ اب ممکن نہ تھا کہ ڈاکٹرگیان چند سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ ابھی مجھے اپنا سامان بھی باندھنا تھا،سومیں نے اسی شب میں ہوٹل ہی سے انھیں خط لکھ کروعدہ خلافی کی معذرت چاہی۔اپنی محرومی پر اظہار افسوس کیااورجواباًان کا۵؍مئی۱۹۸۶ء کاخط موصول ہواجس میں انھوں نے ملاقات نہ ہونے پراپنے قلق کااظہار کرتے ہوئے لکھا:’’تمام مندوبین میںصرف آپ سے ملنے کا اشتیاق تھاکیوںکہ آپ محققین اقبال میں بلند مقام رکھتے ہیں‘‘۔ یہ گیان چند کی بڑائی تھی۔اسی خط میں انھوں نے لکھاکہ’’مجھے یقین ہے کہ آپ سے کبھی نہ کبھی پھرملنا ضرور ہوگا‘‘۔
ان کی توقع یاپیش گوئی کوئی دس گیارہ برس بعد۱۹۹۷ء میں اس وقت پوری ہوئی جب وہ اپنی بیگم کے ہمراہ چند روزکے لیے لاہور آئے۔ ہماری ایک ملاقات تو ڈاکٹر گیان چند کے اعزازمیں دی گئی اس دعوت استقبالیہ میں ہوئی جس کا اہتمام مغربی پاکستان اردواکیڈمی کے ناظم ڈاکٹروحیدقریشی صاحب کی طرف سے کیاگیاتھا۔ دوسری بارراقم اور ڈاکٹرتحسین فراقی ان کی قیام گاہ(محمد طفیل مرحوم کی ’’نقوش منزل‘‘واقع نیومسلم ٹاؤن)پر جاکران سے ملے۔ جاوید طفیل ان کے میزبان تھے۔
۲۴؍اپریل علی الصبح میں تیار ہوگیا۔اتنی دیر میں ظہیر الدین صاحب بھی آگئے۔ہوٹل سے نکل ،انھوں نے مجھے ایک اورساتھی کے حوالے کرتے ہوئے رخصت چاہی کیوں کہ اگر وہ مجھے ریلوے اسٹیشن تک پہنچانے آتے تو ان کادفتر بروقت پہنچناممکن نہ تھا، چنانچہ ان سے الوداع ہوکرہم سکندرآبادریلوے اسٹیشن پہنچے،جہاں سے ریل پرسوار ہوناتھا۔
ریلوے گارڈ سے برتھ کی درخواست کی۔گارڈ نے کہا:کوئی دوگھنٹے بعدفلاں اسٹیشن(نام بھول گیا) سے برتھ مل جائے گی۔
ریل سبک رفتار تھی۔ دوگھنٹے بعد،دوقلی آئے اورانھوں نے میراسامان دوسرے ڈبے میں منتقل کردیا،جہاں برتھ مل گئی۔یہ کام انھوں نے بلا معاوضہ کیاتھااوریہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔میں برتھ پر لیٹ گیا، اونگھتاسوتارہا ۔
حیدرآباد میں تقریباََ ایک ہفتہ گزار کر ،میں واپس جا رہا تھا۔خیال آیا ۔ حیدرآباد کی ریاست ہندوستان میں سب سے بڑی مسلم ریاست تھی مگر اب یہ نابود ہو چکی ہے۔نابودگی کا مختصر قصّہ یہ ہے کہ جون ۱۹۴۷ء میں ریاست نے اپنی آزادی کا اعلان کردیا۔تقسیم کے بعد بھارت سے ایک تین سالہ معاہدہ کیا مگر بھارت نے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کیں تو ریاست حیدر آباد نے ۲۱؍ اگست ۱۹۴۸ء کو اقوامِ متحدہ سے رجوع کیا۔بھارت نے ۱۳؍ ستمبر ۱۹۴۸ء کو حملہ کر کے ریاست پر قبضہ کر لیا۔چند سال بعد ریاست کے تین ٹکڑے کر کے ،انھیںدوسرے صوبوں میں ملا دیا۔اب مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ بھارت کے بعض دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی حالات تشویش ناک ہوتے جارہے ہیں اور اس کااندازہ مجھے دورانِ قیام ایک روزایک دوست کے گھرفسادات کے دنوں کی بعض تصاویردیکھ کر ہواتھا۔ تصاویر سے بالکل واضح تھا کہ پولیس جانب دارَہے۔ مسلمانوں کے مکانوں،دکانوں اور پٹرول پمپوںکو فسادی آگ لگا دیتے ہیں۔فائر بریگیڈ اتنی دیر سے پہنچتا ہے کہ سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ یادآیا کہ ریاست حیدرآباد کے مخدوش مستقبل کا اندازہ علامہ اقبال نے نصف صدی پہلے کرلیاتھا۔ پروفیسرحمیداحمد خاں کی ایک روایت ملتی ہے۔وہ علامہ سے ایک ملاقات کاذکرکرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم چند دوست علامہ کی خدمت میں حاضر تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ ’’کسی نے برّعظیم میں مسلمانوں کے مستقبل کے مسئلے پربات کرتے ہوئے یہ کَہ دیا:’’لیکن حیدرآباد کاانجام کیاہوگا؟‘‘ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر انگریزی میں جواب دیا: ’’حیدر آباد فنا ہو کر رہے گا(Haidarabad must go under) اس لیے کہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے تبلیغ اسلام کے فریضے کوصدہابرس تک فراموش کیسے رکھا‘‘۔(اقبال کی شخصیت اور شاعری، ص۴۳)
مجھے یادآیا کہ مولانامودودی نے بھی ایک خط میں ریاست حیدر آبادکے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے تقریباً اسی طرح کے خیالات ظاہر کیے تھے۔مولانا کی زندگی کا بہت سا عرصہ دکن میں گزرا تھا۔
دسمبر ۱۹۴۷ ء میں حیدر آباد کے کسی شخص نے مولانا سے چند استفسارات کیے۔مولانا نے طویل خط میں جوابات دیے۔اس میں تقسیم ہند کے نتیجے میں دہلی ،مغربی یوپی اور مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کے اخراج (قتل و غارت گری)کے اسباب کا ذکر کیا اور اسی خط میں مزید لکھا کہ یو پی ،بہار وسط ہند کے مسلمانوں کے سرپر تباہی منڈلا رہی ہے حالانکہ یہاں سات آٹھ سو سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا ہے۔جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی عظیم الشان جاگیریں،حیدر آباد کی پائیگاہوں سے کئی گنی زیادہ بڑی جاگیریں قائم رہی ہیں اور جہاں مسلمانوں کی تہذیب اور ان کے علوم و فنون کے عظیم الشان مرکز موجود رہے ہیں لیکن عیاش،دنیا میں انہماک ،فوجی طاقت اور سیاسی اقتداراور انحصار ،اسلام کی دعوت پھیلانے سے تغافل اور انفرادی سیرتوں اور اجتماعی طرز عمل سے اسلام کے اخلاقی اصولوں سے انحراف کا یہ نتیجہ ہوا کہ ا ن علاقوں کی عام آبادی غیر مسلم رہی۔مسلمان نمک کے برابر رہے اور دلوں کو مسخر کرنے کی بجائے معاشی اور سیاسی دباؤ سے گردنیں اپنے سامنے جھکوانے پر اکتفاکرتے رہے۔
علامہ اقبال نے تو مسلمانوں کی تباہی کا صرف ایک ہی سبب بتایا تھا:’’تبلیغ اسلام کے فریضے‘‘سے غفلت، مگر مولانا نے’’اسلام کی دعوت پھیلانے سے تغافل کے ساتھ تباہی کی بہت سی دوسری وجوہ کی نشان دہی بھی کردی تھی ۔
میں حیدر آباد کے خیالات میں غلطاں و پیچاں اور ریل گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے بھوپال سے قریب تر ہو رہی تھی۔
الوداع حیدر آباد،الوداع دکن!!
٭٭٭