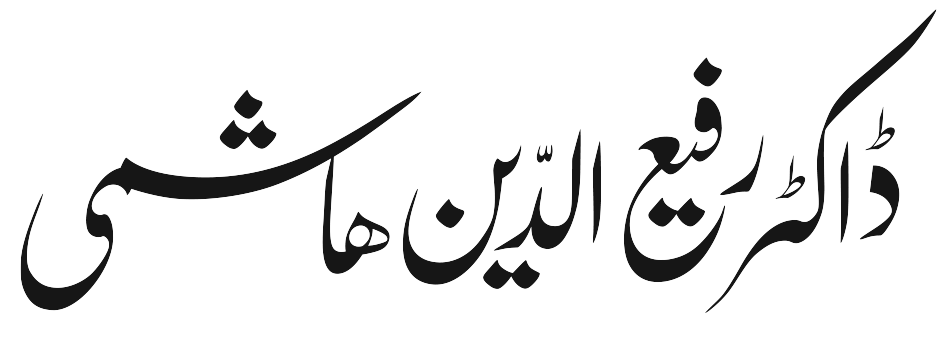٭اُردو کا مقدمہ:غازی علم الدّین
اُردو پاکستان کی قومی زبان ہے لیکن یہ برِ عظیم کے شعر و ادب کی ایک اہم زبان بھی ہے۔ اُردو زبان و ادب کا خاصا بڑا حصّہ ہندوؤں اور سکھوں( رتن ناتھ سرشار ،پنڈت دیا شنکر نسیم، لالہ سری رام ، رام بابو سکسینہ، منشی پریم چند،پنڈت برج نارائن چکبست، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی،تلوک چند محروم،ہری چند اختر، آنند نارائن ملّا، منشی تیرتھ رام فیروز پوری، فراق گورکھپوری ،ڈاکٹر گیان چند ، دیوندر ستیارتھی، راجندر سنگھ بیدی، جگن ناتھ آزاد، کرشن چندر، کنہیّا لال کپور،گیان چند،اورگوپی چند نارنگ) نے تخلیق کیا ہے۔
اگر چہ گاندھی نے یہ کَہْ کر اُردو زبان کو مسترد کر دیا تھا کہ اس کا رسم الخط قرآنی رسم الخط ہے،اور پھر اُردو کے لیےدیوناگری رسم الخط اختیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ (جو بھارت میں تا حال جاری ہے۔)اس کے باوجود اُردو اپنے رسم الخط کےساتھ زندہ ہے۔ دراصل اُردو ایسی سخت جان ہے کہ بھارتی حکمران بھی اسے تاحال ختم نہیں کر سکے۔(کوشش اُن کی جاری ہے۔)
پاکستان میں اگرچہ یہ مسلّمہ طور پر ملک کی قومی زبان ہے،اور جسٹس جوّاد خواجہ نے ۸ستمبر۲۰۱۵ء کو اردو کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا تھا، اس کے باوجود سرکاری ایوانوں میں اور ایک حد تک غیر سرکاری دفاتر اور اداروں میں بھی جملہ اُمور انگریزی زبان میں سرانجام دیے جا رہے ہیں۔ عدالتِ عظمیٰ نے نفاذِ اُردو کا حکم دیا مگر اس کی توہین جاری ہے۔ہم اپنے گلے میں لٹکتا ہوا ذہنی غلامی کا طوق اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
سات مقالات پر مشتمل پروفیسر غازی علم الدّین کےزیرِ نظر مجموعے میں اُردو کی اہمیت، اُس کی مخالفتوں، تعلیمی نصابوں سے اس کے اخراج اور بھارتی حکمرانوں کی طرف سے اُردو کو بھارت سے مکمل طور پر ملک بدر کرنے کی کوششوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ برِ عظیم میں اُردو کی ابتدا ، اُس کے ارتقا اور موجودہ صورتِ حال پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ابتدا میں انگریزوں نے فارسی کی جگہ اُردو کو عدالتی زبان بنا دیا تھا مگر ہندوؤں کو یہ بات پسند نہ آئی ۔ چنانچہ ۱۸۶۷ء میں یوپی کے ہندوؤں نے اُردو کے خلاف تحریک چلائی کہ اُردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے اور اسے دیوناگری رسم الخط میں لکھا جائے۔ سرسیّد احمد خان پہلے مسلمان دانش وَر ہیں جن کی بصیرت نے ہندوؤں کے لسانی تعصّب کے دور رس اثرات کا اندازہ لگا لیا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا تھاکہ اَب ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے کسی مشترکہ عمل کی کوئی اُمّید باقی نہیں رہی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ سر سیّد کا اندازہ سو فیصد صحیح تھا۔
پروفیسر غازی علم الدّین اُردو کا مقدمہ اِس لیے لڑ رہے ہیں کہ اُردو کا تعلق برّ ِ عظیم کے مسلمانوں ، تحریکِ آزادی اور قیام ِ پاکستان سے بہت گہرا اور دیرینہ رہا ہےاور اب استحکام ِ اسلامی جمہوریۂ پاکستان کے لیے بھی اُردو کا نفاذ ناگزیر ہے۔ کتاب کی طباعت و اشاعت معیاری ہے۔ (ناشر: مثال پبلشرز، فیصل آباد۔ قیمت: ۴۰۰ روپے(
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٭سلسلۂ مکاتبت (رشید حسن خاں اور مشفق خواجہ کی دو طرفی مراسلت):ڈاکٹر محمود احمد کاوش
حالیہ برسوں میں مکاتیبی ادب کے سلسلے میں بیسیوں مجموعے سامنے آئے ہیں۔ زیرِ نظر مجموعہ سلسلۂ مکاتبت (رشید حسن خاں اور مشفق خواجہ کی دو طرفی مراسلت) اسی سلسلے کی ایک تازہ اور اہم کڑی ہے۔
رشید حسن خاں(۱۹۲۵ء -۲۰۰۶ء)اور مشفق خواجہ (۱۹۳۵ء-۲۰۰۵ء)اُردو زبان و ادب کے ناموَر عالم، نقّاد اور محقق تھے۔اگر اُردو زبان و ادب کو ایک محل قرار دیا جائے تو مشفق خواجہ اور رشید حسن خاں اِس محل کے دو اہم ستونوں میں شمار ہوں گےجن پر اُردو محل کی خوبصورت عمارت استوار ہے۔ دونوں بزرگوں کے خطوط کے چند مجموعے اِس سے پہلے بھی چھپ چکے ہیں، جیسے : مکاتیبِ مشفق خواجہ بنام رفیع الدّین ہاشمی۔خطوطِ مشفق خواجہ بنام ڈاکٹر طیّب منیر۔مکتوباتِ مشفق خواجہ بنام ڈاکٹر مختار الدّین احمد۔مکتوباتِ مشفق خواجہ بنام نظیر صدیقی۔مراسلت مشفق خواجہ، صدیق جاوید۔رقعاتِ مشفق خواجہ[بنام ڈاکٹر سلیم اختراورطاہرتونسوی]اور باتیں مشفق خواجہ کی[خطوط بنام تحسین فراقی]۔اِسی طرح رشید حسن خاں کے خطوط بھی کئی مجموعوں میں مدوّن کیے گئے ہیں، مثلاً: ہمہ رنگ بنام محمد اسد اللہ ، مکاتیبِ رشید حسن خاں بنام رفیع الدّین ہاشمی۔ ٹی آر رینا نے تین جلدوں میں رشید حسن خاں کے خطوط مرتّب کیے ہیں۔اِن تین جلدوں میں خطوں کی تعداد ۱۸۷۵ ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں رشید حسن خاں کے ۱۰۵ خطوط بنام مشفق خواجہ اور مشفق خواجہ کے ۸۱ خطوط بنام رشید حسن خاں شامل ہیں۔ اِس طرح یہ مجموعہ کل ۱۸۶ خطوط پر مشتمل ہے۔
مشفق خواجہ کے چھوٹے بھائی جناب عبد الرحمان طارق نے چند برس قبل راقم کو خواجہ صاحب اور خاں صاحب کے یہ خطوط عنایت کیے تھے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ میں انھیں مرتّب کر دوں لیکن افسوس ہے کہ راقم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ کام انجام نہ دے سکا۔ ڈاکٹر محمود احمد کاوش مبارک باد کے مستحق ہیں کہ اُنھوں نے یہ بھاری پتھر اُٹھا لیااور یہ مجموعہ نہایت محنت اور عرق ریزی سے مرتّب کر دیا۔خطوں کا متن دونوں مکتوب نگاروںکے اپنے اپنے اصولِ املا میں لکھا گیا ہے۔دونوں کے اُصولِ املا پر کاوش صاحب نے اپنے طویل مقدمے(ص ۱۷-۹۴) میں بحث بھی کی ہے۔ خطوں پر مختصر پاورق حواشی بھی لکھے ہیں اور آخر میں چند خطوں کے عکس بھی دیے ہیں۔ اِس طرح یہ کتاب تدوینِ خطوط کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ ان خطوں میں لسانی اور ادبی بحثیں بھی ہیں، دونوں کے شخصی اور ذاتی حالات اور احساسات و جذبات بھی ہیں اور خطوں سے دونوں کے ذوق اور افتادِ طبع اور دونوں کے ہاں مطالعے کی وسعت کا بھی پتا چلتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مجموعہ نہایت دلچسپ اور اس قابل ہے کہ ادبی ذوق رکھنے والے خواتین و حضرات اس کا مطالعہ کریں۔ (فضلی بکس پبلشرز کراچی ،صفحات:۵۵۱،قیمت : ۱۲۰۰روپے)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٭صحتِ زباں :ڈاکٹر رؤف پاریکھ
زبانیں جوں جوں پھیلتی ہیں، اُن میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اُن میں وسعت بھی آتی جاتی ہے۔ اُردو نسبتاً کم عمر زبان ہے، اس کے باوجود اس کا شمار دنیا کی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے ۔ اُردو کے پھلنے پھولنے کے عمل سے دوسری زبانوں خصوصاً عربی، فارسی اور ترکی کے لفظ بلکہ یورپ کی بہت سی زبانوں کے لفظ بھی اُردو میں شامل ہو گئے۔ اس سے اِن الفاظ کے صحیح استعمال کا مسئلہ پیدا ہوا اور یہ بھی کہ ان نئے(اجنبی) الفاظ کو کس طرح لکھا جائے،یعنی تلفـظ اور املا کے مسائل۔
ڈاکٹر رؤف پاریکھ صاحب لغت و لسانیات اور املا کے موضوعات پر بخوبی دسترس بلکہ مہارت رکھتے ہیں۔ وہ عرصے سے اُردو زبان کے مسائل پراُردو اور انگریزی میں لکھ رہے ہیں۔ (انگریزی میں وہ روزنامہDawn میں ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں۔ )محترم افتخار عارف صاحب نے اپنی نظامتِ مقتدرہ کے زمانے میں پاریکھ صاحب سے کئی مضامین لکھوائے اور اب اُنھی کی فرمائش پر مصنف نے نظرِ ثانی اور اضافوں کے بعد اُنھیں زیرِ نظر کتاب میں مرتّب کر دیا ہے۔ شروع میں ایک سو سے اوپر الفاظ و مرکبات کی فہرست درج ہے ، پھر اُن پر ایک ایک کر کے بحث کی گئی ہے،مثلاً : اب بھی یا ابھی بھی۔ادائی یا ادائیگی۔ اسامی یا آسامی۔ پھولوں کا گلدستہ ۔ چیخ پکار یا چیخ و پکار۔ خاصا یا خاصّہ۔ خط و کتابت کیوں غلط ہے۔ انکسار یا انکساری۔ برّ ِ صغیر یا برّ ِ عظیم۔ پروا یا پرواہ۔ درستی یا درستگی۔استفادہ حاصل کرنا یا استفادہ کرنا۔ان شاءاللہ یا انشاءاللہ۔ دونوں فریقین ۔ طلبہ اور طلبا۔ عوام، مذکر یا مؤنّث ۔حراسانی یا حراسگی۔پاریکھ صاحب نے دلائل اور اسناد کے ساتھ فیصلے دیے ہیں۔
کتاب کے آخر میں مآخذاور الفاظ و مرکبات کا اشاریہ شامل ہیں۔ اخبار نویسوں(کالم نگاروں، رپورٹروں، خبرنویسوں)، اساتذہ، خطیبوں اور اینکروں کوعبرت حاصل کرنے اور کچھ سیکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔(ادارہ فروغِ قومی زبان، اسلام آباد، صفحات:۱۵۴، قیمت:۴۰۰روپے)
٭چراخِ رخِ زیبا: ڈاکٹر محمد علی خاں
ڈاکٹر علی محمد خاں نے ایک ایسی کتاب مرتب کر دی ہے جو بظاہر تو دس خاکوں پر مشتمل ہے لیکن یہ خاکے اپنے اندر دیگر اصنافِ نثر (افسانہ ۔ڈراما ۔انشائیہ۔ داستان ) کی خوبیاں اور اوصاف بھی سموئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض خاکے تو اُن کے قریبی عزیز وں پر ہیں، بعض اساتذہ پر اوربعض کسی نہ کسی حوالے سے نام وَر شخصیات (عبدالسّتارایدھی ۔قاضی برکت علی۔ چودھری احمد سعید۔ سیّد اظہارالحسن رضوی)پر۔
یہ ساری شخصیات وہ ہیں جن سے ڈاکٹر علی محمد خاں زندگی کے مختلف مراحل میں کسی نہ کسی پہلو سے شدید طور پر متأثّر ہوئے۔ اُنھیں ہر شخص میں کچھ ایسی منفرد خوبیاں نظرآئیں جو خال خال لوگوں میں ہوتی ہیں، مثلاً دیکھیے ،سیّد اظہارالحسن رضوی کے خاکے میں علی محمد خاں نے اُن کی ایک گفتگو [ایک قسم کی آپ بیتی ]نقل کی ہے۔وہ بتاتے ہیںکہ: ”مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں دھرم پورہ سے وہاں[کشمیری بازار]تک پیدل ہی جاتا آتا تھا اور حتیٰ الامکان تانگے کا کرایہ بچا لیتا تھا۔ اس زمانےمیں گڑھی شاہو چوک میں شبلی کالج ہوا کرتا تھا اور وہاں شام کی کلاسیں لگا کرتی تھیں۔میں شبلی کالج میں پڑھتا تھا۔ اُس زمانے میں بجلی کا تو کیا مذکور، ہمارے گھر میں لالٹین تک نہ ہوتی تھی اور دِیا جلتا تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر سڑک پر بجلی کے کھمبے کے بلب کی روشنی میں رات گئے تک پڑھتا اور اپنا آموختہ یاد کرتا۔ ان حالات میں مَیں نے شبلی کالج سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ “
ایک ضمنی کیریکٹر پٹھان چوکیدار کا ہے۔ علی محمد خاں صاحب،ایک روز رضوی صاحب سے ملنے کے لیے اُن کے پریس پر پہنچے۔وہ موجود نہ تھے۔ لکھتے ہیں: ایک بڑی بڑی مونچھوں والے لمبے تڑنگے خوں خوار قسم کے پٹھان چوکیدار نے مجھے اُن کے آفس میں بٹھا دیا اور مجھے کنارا ٹوٹے ایک مگ میں چائے اور ساتھ ہی اسی رنگ کی کنارا ٹوٹی ایک پرچ میں چینی لا کر میرے سامنےرکھ دی۔ اور بغیر پوچھے ایک چٹکی بھر چینی چائے میں ڈال دی اور قاہرانہ وجابرانہ انداز میں،چائے پینے کا حکم صادر کیا۔ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور نہ جانے میں انکار نہ کر سکا۔ جب میں نے ملتجیانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو پٹھان کہنے لگا: اب تو کیا کہتی ؟ میں نے کہا: خان صاحب، میں کچھ نہیں کہتی بس ایک چمچ مانگتی ۔وہ فوراً میرے نزدیک آیا اور اس نے اپنی انگشت شہادت کو گرم چائے میں چمچ کی مانند گھمایا اور پھر خشمگیں نگاہوں سے میری طرف دیکھا ،گویا یہ کَہْ رہا ہوکہ اب بھی پیتے ہو یا یہ چائے میں تمھارے منہ میں انڈیل دوں۔ میں نے یہ سوچ کر چائے پینا شروع کی کہ سقراط کو بھی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا تو اس نے ایک ہی گھونٹ میں غٹا غٹ پی لیا تھا۔ اتنے میں اظہار صاحب اپنے آفس میں داخل ہوئے تو میری جان میں جان آئی۔ تمام واقعہ اُنھیں سنایا تو کہنے لگے: پروفیسر صاحب، جب سے یہ آیا ہے میں بڑے چین میں ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے پریس میں بہت چوریاں ہوتی تھیں، وہ سب رک گئی ہیں۔یہ بڑا ہی وفا دار ملازم ہے مگر ہے ذرا اکھڑ اور جاہل۔ میں آپ سے اس کی پُرخلوص حماقت پر معافی کا خواستگار ہوں۔(ص۱۵۳)
ضمنی کیریکٹروں میں جمال الدین ہر فن مولا اور با ہمّت شخص تھے۔ انتہائی ناسازگار حالات میںبھی اُنھوں نے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا۔ وہ علّامہ اقبال کے اِس شعر کا مصداق تھے :
ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے
آتے ہیں جو کام دوسروں کے
ڈاکٹر علی محمدخاں کے ان خاکوںسے ہمیں شخصیات کے علاوہ ،گزرے زمانوں میں مختلف مقامات، شہروں اور محلّوں کے اچھے برے ماحول اور فضا کا بھی اندازہ ہوتا ہےاور قیام ِپاکستان کے پس منظر اور وطنِ عزیز کے مسائل ، الجھنوں اور الجھاووں کا بھی پتا چلتا ہے۔ ان خاکوں کے قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پا کر بھی ،کیوں پستی اور پسماندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ (سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور، صفحات:۱۹۱،قیمت:۹۰۰ روپے)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٭ڈاکٹر تحسین فراقی، شخصیت اور فن:ڈاکٹر طارق ہاشمی
اکادمی ادبیاتِ پاکستان نے ایک زمانے میں ”پاکستانی ادب کے معمار“کےتحت ملک کے نام وَر ادیبوں اور شاعروں کے”شخصیت اور فن“ پر مختصر تعارفی اور تجزیاتی تعارف لکھوانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔اس کے تحت نہ صرف اُردو ، بلکہ پشتو، ہندکو، سندھی، بلوچی، براہوی زبانوں میں لکھنے والوں پر بھی تقریباً دو سو کتابیں لکھوا کر شائع کی گئیں۔زیر نظر کتاب اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ ( راقم الحروف کی علّامہ اقبال : شخصیت اور فن کے پشتو، سندھی، پنجابی اور انگریزی تراجم بھی کرائے گئے، جن میں سے اوّل الذّکر دو تو چھپ گئی تھیں ،باقی تراجم کا معلوم نہیں کیا ہوا؟ممکن ہے ،اکادمی ادبیات کے کسی گودام میں پڑے ہوں۔)
اُردو تحقیق و تنقید اور شعر و ادب میں ڈاکٹر تحسین فراقی(پ:۱۷ ستمبر ۱۹۵۰ء) کا نام اور کام محتاجِ تعارف نہیں۔وہ ایک نام وَر اور معتبر نقّاد، محقّق اور شاعر ہیں۔ درس و تدریس سے وابستگی کےابتدائی زمانے میں وہ مختلف سکولوں اورکالجوں (لیّہ، شرق پور،لاہوراور ۳۳۳ گ ب)میں پڑھاتے رہے۔۱۹۸۴ء میںپنجاب یونی ورسٹی اورینٹل کالج لاہور کے شعبۂ اُردو سےوابستہ ہوئے۔چند برس کے لیے حکومتِ پاکستان نے اُنھیں تہران یونی ورسٹی کی اُردو چیئر پر ایران بھیجا جہاں اُنھوں نے شعبۂ اُردو قائم کیا۔اورینٹل کالج سے صدرِ شعبۂ اُردو کے منصب سے وظیفہ یاب ہونے کے بعد” اُردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ“ میں مدیر رہے۔بعد ازاں پانچ برس تک مجلسِ ترقیِ ادب لاہور کے ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔
زیرِ نظر کتاب کا پہلا باب فراقی صاحب کے سوانح اور احوال و آثار(خاندانی پس منظر۔تعلیمی سفر ۔ ازدواجی زندگی۔ تدریسی سفر۔ بیرونِ ملک تدریسی ذمّہ داریاں۔ علمی و ادبی کاوشیں اور سرگرمیاں۔ منصبی مصروفیات۔امتیازات و اعزازات۔ بیرونِ ملک سیمی ناروں اور کانفرنسوں میں شرکت۔ اندرونِ ملک بین الاقوامی علمی مجالس میں شرکت۔علمی اداروں کی رکنیت۔ تصانیف و تالیفات)پر مشتمل ہے۔دوسرے باب کا عنوان ہے:” ڈاکٹر تحسین فراقی کی تحقیق و تنقید۔“اس باب میں اُن کی تحقیق و تنقید کے موضوعات اُن کے فکر و نظر کے رجحانات ،طرزِ نقد اور زاویۂ نقد کا جائزہ لیا گیا ہے۔یہ باب خاصا مفصّل ہے اور فراقی صاحب کی کتابوں بلکہ اُن کے مضامین پر بھی کلام کیا گیا ہے۔تیسرا باب تحسین فراقی کی شاعری سے بحث کرتا ہے۔یہ باب مختصر ہےاور اس کا کچھ حصّہ ان کے منتخب کلام پر مشتمل ہے۔چوتھے باب میں فراقی صاحب کی ترجمہ نویسی (انگریزی سے اُردو-فارسی سے اُردو)پر اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔آخر میں ڈاکٹر تحسین فراقی اور اُن کی تخلیقات کے بارے میں ناقدین (جن میں اُن کے چند شاگرد بھی شامل ہیں)کی آرا نقل کی گئی ہیں۔
اکادمی ادبیات کا یہ سلسلہ بہت مستحسن ہے۔ڈاکٹر طارق ہاشمی فراقی صاحب کے شاگرد ہیں ۔ اُنھوں نے بڑی محنت سے یہ کتاب مرتّب کی ہے اور اپنے استاد کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔پہلے دو باب بھرپور ہیں لیکن آخری دو ابواب کی تسوید میں مزید توجہ کی ضرورت تھی۔(اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد۔ صفحات ۲۱۲۔ قیمت: مجلّد ۳۰۰روپے۔ غیر مجلّد :۲۶۰ روپے)
٭را اور بنگلہ دیش: محمدزین العابدین
متحدہ پاکستان سے مشرقی پاکستان کی علاحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب ،واقعات اور نتائج پر مبنی اردو اور انگریزی میں بیسیوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلے کی ایک آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے۔
محمد زین العابدین نے سقوطِ مشرقی پاکستان سے پہلے مکتی باہنی میں شامل ہو کر بھارت جاکر مار دھاڑ کی تربیت حاصل کی، پھر بھارتی فوجوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں شریک رہے۔ کہتے ہیں کہ ۱۹۷۱ء سے پہلے ایک بزرگ نے مجھے سمجھایا کہ بھارت مسلمانوں کا کبھی مخلص اور سنجیدہ دوست نہیں ہو سکتا، مگر میری آنکھوں پر پاکستان دشمنی کی پٹّی بندھی ہوئی تھی اور ۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ء کے بعد جب ’’بھارتی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار شروع کی، بھارتی فوجیوں کے ہاتھ جو کچھ لگا، وہ بھارت لے گئے۔ لوٹ مار میں آسانی کے لیے چھوٹے بڑے شہروں،قصبوں، تجارتی مراکز، بندر گاہوں اور صنعتی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ۔ بھارتی فوجی صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ پنکھے اور نل تک نکا ل کر لے گئے ۔ بھارتی فوج کی ہزاروں گاڑیوں میں لوٹا ہوا مال بھارت پہنچادیا گیا اور یہ ساری لوٹ مار بھارت کی طرف سے اعلیٰ ترین سطح پر دی جانے والی اجازت کے بغیر ممکن نہ تھی، تب میری آنکھوں پر بندھی پٹّی کھلی‘‘۔
مصنف نے چشم دید واقعات ،تجربات اور تحقیقات کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ سقوطِ مشرقی پاکستان میں بنیادی کردار بھارت کے خفیہ جاسوسی ادارے ”را“کا ہے۔ ”را“کی بنیاد کو ٹلیہ کی ارتھ شاستر ہے۔ ”را“ بھارت کا سب سے طاقت ور ادارہ ہے۔ چند سال پہلے تک اس کا بجٹ ۱۵ ہزار کروڑ تھا۔ اس کا ہدف پاکستان، سری لنکا ، بھوٹان، نیپال وغیرہ کو بھارت کا حصّہ بنا دینا ہے۔ مصنّف نے ”را“کے طور طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اہلِ پاکستان (عوام اور حکومت) اس کا اِدراک کر کے اپنے دفاع کی تدابیر کریں۔ کتاب کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کی ضرورت ہے۔(اسلامک ریسرچ اکیڈمی ،کراچی ۔صفحات: ۲۸۸،قیمت :ایک ہزار روپے )
٭داستانِ عزم ،خودنوشت: ،ڈاکٹر عبدالقدیر خان
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق برعظیم کی مردم خیز ریاست بھوپال سے ہے۔ ان کے جدِّ امجد شہاب الدین غوری کی فوج کے ایک کمانڈر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد بھوپال میں مقیم ہو گئے تھے۔
عبدالقدیر خان بھوپال سے میٹرک کرنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں پاکستان چلے آئے۔ کراچی سے بی ایس سی کیا۔ ۱۹۶۱ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے ۔ ہالینڈ میں بھی زیرِ تعلیم رہے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انھوں نے یورپ کے بعض تحقیقی اداروں میں کام کیا اور اپنے فن پر پوری طرح دسترس حاصل کرلی۔ بعض غیر ملکی اداروں کی جانب سے پُر کشش پیش کشوں کو نظر انداز کرکے وہ پاکستان آ گئے اور یہاں اٹامک انرجی کمیشن میں جوہری بم بنانے کا پروگرام شروع کیا۔
ایٹم بم بن گیا، اس کا تجربہ بھی ہو گیا۔ بعد ازاں خان صاحب نے سماجی اور دینی خدمات کے سلسلے میں متعدّد ادارے قائم کیے۔ جنرل مشرف نے خان صاحب کی کردار کشی اور تذلیل کی مگر مشرف کی رخصتی کے بعد انھیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ’نشانِ امتیاز‘‘ سے نوازا گیا۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک منجھے ہوئے قلم کار بھی تھے۔ ادبی اور شعری ذوق بھی رکھتے تھے۔ سات آٹھ کتابیں ان سے یاد گار ہیں۔انھوں نے روز نامہ جنگ میں مستقل کالم لکھنا شروع کیا۔ ان کا لموں میں وہ اپنی آپ بیتی بھی لکھتے رہے۔ اس آپ بیتی میں ایٹم بم بنانے تک کے مراحل کے ساتھ کہوٹہ لیبارٹری کے سائنس دانوں اور عام کارکنوں میں مثبت اور منفی کرداروں کی سرگرمیوں کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ملک کی سا لمیّت سے متعلق معاملات میں بھی کرپشن دخل اندازی کرتی ہے مگر سابق صدر غلام اسحاق خان جیسے محبّ ِ وطن نے ممکنہ حد تک ڈاکٹر عبدالقدیرخان کی پشت پناہی کی۔ انھوں نے معروف صحافی زاہدملک کے نام ایک خط میں خان صاحب کی شخصیت وکارکردگی اور ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں ان کی کاوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔
خط کے آخر میں غلام اسحاق خان لکھتے ہیں:ڈاکٹر عبدالقدیر خان حقیقتاً ایک اچھّے اور عظیم انسان ہیں۔ اس لیے کہ اپنے ملک کی ترقی اور اپنی قوم کی فلاح وبہبود سے زیادہ عظیم کوئی مقصد ہو نہیں سکتا اور اسی مقصد کی خاطر وہ جیے اور جیتے ہیں۔ انھوں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اور جو بھی کارنامے انجام دیے، وہ اپنی گواہی خود دیتے ہیں اور یہ کارنامے ایسے ہیں کہ ان الفاظ سے کہیں زیادہ بلند آواز سے یہ اپنا اعلان خود کرتے ہیں جو الفاظ ان کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں ۔ ان کی زندگی کا آئینہ یہ مشہور فارسی مقولہ ہے: مُشک آنست کہ خود ببوید، نہ کہ عطّار بگوید (مشک وہ ہے جو خود خوشبو دیتا ہے ، نہ کہ وہ جس کا دعویٰ عطار کرے )۔ (قلم فائونڈیشن ،لاہور۔ صفحات :۱۴۶+۵۶ ۔قیمت :پندرہ سو روپے۔)
٭دنیا میرے آگے ،افشاں نوید
محترمہ افشاں نوید کے ۴۱ ،اخباری مضامین پر مشتمل یہ ان کا تیسرا مجموعہ ہے، جو ان کی ”قلبی واردات“کا لفظی اظہار ہے۔ ’’میں نے جو دیکھا ، سوچا، محسوس کیا ، اس قلبی واردات کو قلم کی زبان دے دی‘‘۔ چند عنوانا ت دیکھیے :عصر کی قسم۔ فتنوں سے آگاہی۔ میدانِ کربلا ۔ہماری تاریخ کا چوراہا۔ ماہِ صیام کل اور آج۔ علّامہ اقبال اور آداب فرزندی ۔ بات ہے اقدار کی۔ تمھی سے اے مجاہدو! جہان میں ثبات ہے۔ قانونِ تحفظِ نسواں اور بی آپا۔ ۱۶ دسمبر ، یومِ سقوطِ ڈھاکا۔ نصاب اور استاد ۔ اسٹیفن ہاکنگ ۔ سڈنی ائر پورٹ۔ یومِ کشمیر ۔ شرمین چنائے عبید ۔ آپ کے نام ۔
کتاب کا ہر کالم لکھنے والے کے حسّاس دل ودماغ کا آئینہ دار ہے۔ مصنّف کے جذبات لفظوں کے قالب میں ڈھل کر کالم بن گئے ہیں۔ ایک کالم میں فلم ساز شرمین عبید چنائے کے حوالے سے لکھا ہے:’’شرمین صاحبہ، آپ نے کیمرے کے توسّط سے ساری دنیا کو پاکستانی عورت کا جھلسا ہوا چہرہ دکھایا اور یہ ڈاکو منڑی آسکرایوارڈ کے لیے منتخب ہو گئی۔ آپ آسیہ اندرابی کے دُکھ کو بھی محسوس کیجیے۔ غلام احمد مسعودی کی صاحبزادی آمنہ مسعودی کو ضرور دکھایئے، جس نے بھارتی اہل کار کے سامنے مزاحمت کی اور شور مچایا تو ظالم نے آمنہ کا گلا دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آپ پر کشمیر اور پاکستان کا یہ فرض ہے کہ آپ آسکر ایوارڈ کی اگلی نامزدگی کے لیے اپنی ڈاکومنٹری کا عنوان: ”کشمیر کی مظلوم عورت “کو بنائیں‘‘۔
افشاں نوید ہر واقعے اور ہر سانحے کو اسلامی نظریۂ حیات کی روشنی میں دیکھتی اور اس پر رائے ظاہر کرتی ہیں ۔ شاہ نواز فاروقی لکھتے ہیں:’’بلا شبہہ افشاں نوید صاحبہ کے کالم پڑھ کر خیال آتا ہے کہ ان کے لیے کالم نگاری ایک مشن ہے۔ ان کے کالموں پر ادبی مطالعے اور ادبی ذوق کا گہرا سایہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے کالموں میں پختگی، گہرائی اور سنجیدگی کی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں‘‘۔ (ادارہ بتول،لاہورصفحات :۲۲۴،قیمت: ۴۴۰ روپے ۔)
(ختم شد)